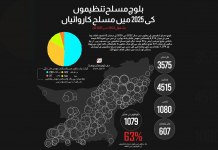بلوچ عظیم رزمیہ کا سب سے بڑا داستان گو چلا گیا
تحریر: منظور بلوچ
دی بلوچستان پوسٹ
نہ جانے آج کیا خاص بات ہے کہ لکھنے کا مقصد کیے بیٹھا ہوں، لیکن بات نہیں بن رہی، الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے، جیسے سارے الفاظ خفا ہوں یا خوابیدہ ہوں، یا مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔یہ الفاظ بھی عجب گورکھ دھندا ہیں، کبھی دماغ میں کلبلانے لگتے ہیں، ان کو اپنے اظہار کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور کبھی بالکل ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، آڑھی ترچھی لکیریں کھینچے چلا جا رہا ہوں، لیکن معاملہ نہیں ہو پا رہا۔ تحریر کا مسئلہ بھی میرے سامنے شاعری کی طرح ہے، شاید کوئی بھی نوشت قافیہ پیمائی سے نہیں بلکہ آمد سے آتی ہے، اور جس تحریر میں قافیہ پیمائی ہو، وہ دل کو ویرانے کا احساس دلاتی ہے، دل تو کبھی کا ویران تھا، آج تو بالکل صحرا بن بیٹھا ہے، جب تک بات نہیں ہوتی، بات نہیں بنے گی، ایک لکھنے والا (جس کا دعوے دار نہیں) سارا وسیلہ، اوزار و آلات الفاظ ہی ہوتے ہیں، کھیل ویسے دیکھا جائے تو سارا ہی الفاظ کا ہے، انہی لفظوں کے ذریعے ہم پر حکمرانی کی جاتی ہے، اور انھی الفاظ کے سہارے جبر کے بند توڑے جاتے ہیں۔
تحریر میں جب تک آمد کے ساتھ دل کا ارادہ شامل نہ ہو وہ نوشت ساتھ نہیں دیتی، کبھی وہ چھپ جاتی ہے، کبھی فقط ایک جھلک دکھلا جاتی ہے، کبھی تو بالکل اجنبی بن کر رہ جاتی ہے۔
میں نے جب بھی لکھا، تو آمد کی کیفیت کے ساتھ لکھا، بقول انتظار حسین لکھنا (افسانہ) تو تیر اور تکے کی بات ہے، نشانے پر لگا تو تیر ورنہ تکا۔خیر اس الفاظ کی دنیا میں ہم جیسے تکا لگا کر ہی کام چلا لیتے ہیں، لیکن آج تکا بھی بے تکا سا لگ رہا ہے۔
کئی دنوں سے ارادہ تھا کہ اپنے مغنی کے بارے میں لکھوں، جس نے اپنی قوم کو امید کے نشاط انگیز گیت سنائے، اس کی ہر ایک بات میں ایک جھلکتا نغمہ تھا، اس کے پاس المیوں کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا، لیکن یہی المیہ جب اس کی گفتگو میں ڈھل جائے تو المیہ بھی شیریں لگتا اور آگ اور خون کی باتیں شعلوں کی طرح لپک لپک کر جذبات کے جنگل میں آگ لگا دیتے۔
کیا جوان، کیا پیر، جس نے اس مغنی کو سنا ہے اس کا وار کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا، اس کے بولوں میں ایک طلسماتی فضاء ہوتی، اس کے ایک جملہ سے اسلام آباد کی غلام گردشوں میں لرزہ طاری ہوتا، اس کے فقط ایک جملے نے، جو اس نے نواز شریف کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کے دوران کہاتھا، اس جملہ نے حامد میر کی پوری زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ پسندیدہ صحافی، طالبان اور اسامہ بن لادن کے انٹرویوز کی وجہ سے عالمی شہرت یافتہ بن چکا تھا، لیکن اس سے بھول ہو گئی اس نے نا دانستگی میں اس ایک جملے میں چھپے اس آگ کی تپش کو محسوس نہیں کیا، جس نے آگے چل کر اس کو درجنوں گولیوں کا نشانہ بنانا تھا، بظاھر اس کے جملے سیدھے سادے ہوتے لیکن ان میں بے رحمی کا وہ نشتر ہوتا جس کو لگتا، صاف سینے پر لگتا، پھر وہ کبھی اس کے اثر سے بچ نہیں پاتا۔اس کا تروتازہ دماغ گویا جام جم تھا، جس میں وہ ساری دنیا کا احوال دیکھ اور پڑھ لیا کرتا تھا.
گویا وہ مستقبل شناس تھا، اس نے جو کہا، ویسے ہی ہوتا رہا، جھنوں نے ہمارے اس مغنی کی سیلگ ہیرسن کے ساتھ اس کی کتاب میں انٹرویو پڑھ رکھا ہے، اسے ایک بار پھر پڑھے، اسی کی دہائی کا یہ انٹرویو آج کی باتیں بیان کر رہا ہے۔
بستی بستی پربت پربت گاتا جائے بنجارا
لے کر دل کا اک تارا
ہاں دل کے ایک تار سے جانے وہ کیسے کیسے سروں کو چھیڑ دیتا۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے اس مغنی کو اس حوالے سے دیکھا نہیں، یہ تو ذوق کی باتیں ہیں، بھلا کون جانے اس ذوق کو، جب اپنے ہی گھر گلشن میں آگ لگی ہو، وہ بھی جلے ہوئے گلشن کا تذکرہ کرتا تھا، اس کی صاف گوئی ہلچل مچا دیتی تھی، اس کی زندگی میں وہایک افسانہ ہی بنا رہا، جب وہ ہماری محفل سے اٹھ کر جا چکا ہے، اب وہ بلوچ تاریخ کا ایک افسانوی کردار بن چکا ہے۔جس پر برسوں لکھا جائے گا، بولا جائے گا، بلوچ تاریخ اس مغنی کے نغموں کے سوا پھیکی رہے گی۔
خیر،اب الفاظ کچھ کچھ ساتھ دینے پر آمادہ نظر آرہے ہیں، خالی الذہن ہو کر کچھ سطریں لکھنے کی کوشش میں ہوں، میں نہیں جانتا کہ بات بنتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ مد مقابل کوئی عام شخص نہیں، پوری تاریخ ہے، اس تاریخ میں اس کا کردار بہت واضح ہے، وہ بڑے قد کا آدمی تھا، لیکن جس طرح ہم نے اپنے ہیروز کی اپنی زندگی میں قدر نہیں کی، اسی طرح ہمارے اس مغنی کے ساتھ بھی ہوا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کی قوم کی چاہت نہیں ملی، جب ہمارا یہ مغنی،اپنے دیرینہ رفیق میر غوث بخش بزنجو کے انتقال پر برسوں بعد وطن لوٹا تو اس کے استقبال کا عالم یہ تھا کہ جلوس کا ایک سرا لکپاس سے پرے تھا، تو دوسرا سرا ایم پی اے ہاسٹل۔
لوگ اس کو سننا چاہتے تھے، بھیڑ سی لگی ہوئی تھی، 88 ء کے انتخابات میں بی این وائی ایم سے بننے والی بی این ایم نے شہید نواب اکبر بگٹی سے اتحاد کرکے بلوچستان نیشنل الائنس قائم کر چکی تھی جس میں ”مینگل،مری آئیں گے، انقلاب لائیں گے“ کے نعرہ پر الیکشن جیتے اور بلوچستان میں اپنی وزارت قائم کی۔
لیکن اب وہ مغنی اس کرہ ارض کی سیر کے بعد جا چکا ہے، وہ چلا گیا۔۔۔۔بہت دور چلا گیا۔ اب وہ ہماری صدائیں نہیں سن سکے گا، لیکن اس نے اپنی گفتگو اور خطابت سے جو سر شاری پیدا کی تھی، وہ اب بلوچوں کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔
ہاں۔۔۔۔یہ بات سچ ہے کہ بلوچ قوم کی عظیم رزمیہ کا عظیم رزم نگار اور داستان گو چلا گیا۔
زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا
ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے
جانے والے کے روشن خیالات اور بے حد ترو تازہ اور توانا ذہن نے اس عظیم رزمیہ داستان کے کئی رنگ و روپ اور بلوچ المیہ کو بیان کرنے کیلئے نہ جانے کتنی دھنیں اور طرزیں تخلیق کی تھیں،جن کو شاید کوئی ہو، جو ڈی کوڈ کر سکے اور ان دھنوں کو ایک نئی سج دھج دے سکے،بھلا یہ بھی ممکن ہے۔لیکن نا ممکن تو کچھ بھی نہیں۔جانے والے نے اپنی سر زمین سے عشق کی جتنی بھی دھنیں تخلیق کیں اب کوئی اور ذی شعور شخص ان کو سن نہیں سکے گا۔انھیں سننے کیلئے بھی جانے والے کی طرح ایک توانا اور باذوق ذہن کی ضرورت پڑے گی۔
جانے والے نے وہ تمام طرزیں جو ایک نئی قسم کے حزنیے جن کو جوشیلے راگ یا دیپک راگ میں تخلیق کیئے جنکا جادو نصف صدی تک بلوچ دنیا میں سر چڑھ کر بولتا رہا۔جانے والے نے اس عظیم المیہ کو ایک عظیم اداسی کا رنگ تو دیا لیکن اس کو تمام خوف اور واہموں سے آزاد بھی کروایا۔
آج میں اپنی تمام تر کم فہمی کے باوجود سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مرثیہ نگار چلا گیا، جو شاعری کی خوشبو اور موسیقی کے جادو کو اپنی تقریروں میں گھولنے کا ہنر بخوبی جانتا تھا۔
وہ قوم جس کی روح کے زخموں کا علاج کبھی نہیں ہو سکا، ان زخموں میں سے ایک زخم اسد کی گمشدہ نوجوانی کا بھی تھا۔جسے شاید ہی کبھی اس عظیم داستان گو نے کہیں بیان کیا ہو۔وہ ایک کرب میں پوری زندگی جیتارہا لیکن اس نے اپنے کرب کو اپنے دل کے آس پاس کہیں چھپائے رکھا، اس کرب کو اس نے کبھی بھی بلوچوں کے عظیم رزمیہ کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایک نجات دہندہ کیلئے شاید یہی آرڈر آف دی ڈے ہوگا۔
ہمارا یہ عظیم داستان گو،نجات دہندہ ایک باپ کا شفقت بھرا دل بھی رکھتا تھا۔اس نے اس جنگ کو ایک خنجر کی طرح اپنے دل میں خود ہی پیوست کیئے رکھا، وہ اپنی انگلیاں اپنے دل کے لہو میں ڈبوئے رکھنے کے باوجود جب بھی مجلس آراء ہوتا تو اس کا ایک ایک لفظ اپنی مٹی کی محبت میں شہد کی طرح گھلنے لگتا، گویا وہ مصری کی ڈلی ہو، اتنی بڑی، گہری اذیت جو روح کو گھائل کرتی رہے۔ وہ اسی کرب کو لیئے مجلس نشین تو ہوتے لیکن اپنے اندر کے داستان گو سے وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہو گا، یہ بات تو ہم نے ان سے کبھی پوچھی ہی نہیں، جو سوال پوچھا ہی نہیں گیا اس کا کبھی جواب بھی نہیں ملا۔ وہ بیانوے سال تک ہمارے ساتھ رہا،جیا،جیل اور زندان دیکھے، جلا وطن کے دن گزارے،، لیکن ہم وہی ایک بات ان سے نہیں پوچھ پائے،ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اس عظیم داستان گو نے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی تہنائی،اپنی عظیم تنہائی اور لمبی جدائی کو سینے میں لیئے جیتا رہا،اس لمبی جدائی اور تنہائی کے سوز نوا کو کون بھول سکتاہے کیونکہ یہ چوٹ تو بالکل برابر دل پر لگائی گئی تھی۔چوٹ، چوٹ میں فرق ہوتا ہے، کچھ چوٹ جسم پر لگتے ہیں، اپنی بہار دکھلا کر چلے جاتے ہیں،لیکن کچھ ایسے زخم بھی ہوتے ہیں لمبی جدائی کا اعلان نامہ لیکر روح پر حملہ آور ہوتے ہیں،پھر یہ زخم دل کے لہو سے بڑھنے لگتے ہیں، پنپنتے لگتے ہیں۔
لیکن ہمارے داستان گو کا ذہن صاف اور اجلا تھا وہ بولتا تو کوئی اور بول نہیں پاتا، گویا وہ ایک ایسا ساحر تھا جس نے تمام الفاظ کو ایک جادوگر کی طرح اپنے قابو میں کیئے رکھا تھا۔ وہی ایک عام سا لفظ جسے لوگ دن رات بیان کرتے، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ لیکن جونہی وہ لفظ ہمارے داستان گو سے مس ہوتا تو اس کی قسمت بدل جاتی، اس کے معانی بدل جاتے اب وہ ایک بے جان لفظ یا ایک مردہ جملہ یا مرا ہوا محاورہ نہیں ہوتا،وہ ایک جیتا جاگتا مظہر بن جاتا۔اور لوگ دھک سے رہ جاتے۔گویا داستان سنانے والا خاموش نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ داستان کو درمیان میں چھوڑ دے۔اس کے زیرو بم بیان نہیں کرے۔لیکن یہ تو اس کی اپنی مرضی پر منحصر تھاکہ وہ کس لفظ کو اپنے بولوں کا جادو دے کر جگنو بنا ڈالے۔اور جانے کب اندھیری،تاریک رات میں روشنی کا جھماکا ہوجاتا،جیسے سنگین سے سنگین سیہ رات میں رنگ اور نور کی بارشیں ہو رہی ہوں۔اس نے کچھ کہا یا نہیں کہا، لیکن بلوچوں کی داستان کو ایک رنگ ایک روپ بخشا۔ اس کو معنی کا پوشاک پہنایا، وہی زخم جو قدموں کو چور چور کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ بلوچی راہ کا کوئی رہگزر ہمت ہار دیتا، ایک آوازدور شفق سے ایک گرجتے برستے بادل کی طرح خاموشی کی فضاء کو چیر دیتا اور ہار دینے والا رہگزر اپنے اندر ایک نیا جوش،نیا ولولہ محسوس کرتا، وہ پھر چلنے لگتا، اپنے منزل اور مقصد کی جانب۔ اور آج بھی یہ سفر جاری ہے۔
اگر بابا مری اس قوم کے دماغ تھے، تو شہید نواب بگٹی اس قوم کے آہنی ہاتھ تھے اور سردار عطاء اللہ مینگل اس قوم کا داستان گو تھا۔ اب نہ بابا مری رہے، نہ نواب بگٹی، نہ سردار عطاء اللہ۔قدرت کی ستم ظریفی دیکھیئے کہ ایک ہی قد کاٹھ کے تین بڑے نجات دہندہ ہم عصر تھے، انہوں نے بلوچوں کے عظیم رزمیے میں اپنی اپنی بساط سے بڑھ کر حصہ ڈالا۔کیا سردار عطاء اللہ مینگل کی گرج دار آواز نہ ہوتی،توکیا بلوچ قوم کو اپنے وجود کا احساس ہوتا۔
سردار عطاء اللہ مینگل سے اور بلوچ قومی جدوجہد سے ایک دھندلی سی ملاقات مجھے یاد ہے جب میں شاید پرائمری جماعت کا طالب علم تھا، ایک دفعہ مرے والد نے مجھے ایک تصویر دکھائی اور کہا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ تصویر سردار عطاء اللہ مینگل کی تھی اور وہ پس زندان تھے۔ یہ تھا بلوچ قومی جدوجہد سے میرا پہلا تعارف، پھر مرے ابا جان اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات دہراتے تھے کہ سردار عطاء اللہ مینگل کی وزارت سے قبل ہماری یہ حالت تھی کہ ہم جناح روڈ پر براہوئی زبان بولنے سے بھی ہچکچاتے تھے۔لیکن اس آٹھ ماہ کی حکومت نے بلوچوں کو ایک نیا حوصلہ اور اعتماد بخشا۔ دیکھا جائے تو آج بلوچ جس رزمیے سے دوچار ہیں، یا بلوچستان کے وسیع و عریض علاقے میں خاک اورخون کی جنگ ہے، اس کے بیج اسی وزارت میں ڈالے گئے، جسکے وزیر اعلی سردار عطاء اللہ مینگل تھے۔ ان کی شخصیت میں جو رعب اور دبدبہ تھا،اس پر مستزاد ان کی گفتگو کا جادو، بھلا ذالفقار علی بھٹو کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا۔بھٹو اسی زعم میں مارا گیا کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا مقرر تھا اور یہ ایک سفید جھوٹ تھا۔ بھلا سردار مینگل کی موجودگی میں تقریر کا فن اس کے اسرار و رموز کون جانے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ شہید نواب اکبر بگٹی نے اپنے رشک کا اظہار یوں کیا تھا کہ کاش وہ بھی سردارمینگل کی طرح مقرر ہو سکتے۔ لیکن یہ فن تو صرف اسی ایک شخص کے ہاں تھا، جسے قدرت نے دل کھول کر نوازا تھا۔ ہمارے ہاں اکثر نیم پڑھے لکھے، نیم خواندہ قسم کے لوگ زچ ہوکر کہتے ہیں کہ بھلا باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ آدمی کو عملی ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کس بات کی بات کرتے ہیں اور عمل سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟
لیکن جس طرح ایک طرح ایک عظیم نغمہ تخلیق ہوتا ہے، وہ صرف گلوکار کا ہی کمال نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی اور فن کار بھی ہوتے ہیں، خیال کو شاعر اپنی شاعری میں اتار دیتا ہے۔ پھر موسیقار اس کو اس کی روح کے مطابق ایک دھن سے نوازتا ہے، اس کے بعد آرکسٹرا کی باری آتی ہے۔ ایک فن کار وہ بھی ہوتا ہے جو اس عظیم نغمے کی موسیقی کو ترتیب دیتا ہے۔وہ سارے سازندے بھی تو کمال کے فن کار اور تخلیق کار ہوتے ہیں، جو نغمے کو فضاء کو شروع سے لیکر آخر تک بڑینفاست اور کمال کی حد تک نازگی سے تھامے رکھتے ہیں۔ عظیم نغمے نہ ہی روز جنم لیتے ہیں، نہ ان میں کوئی ایک فرد شامل ہوتا ہے۔ البتہ گانے والا سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ، شاعر، موسیقار کے چہرے بھی ابھرنے لگتے ہیں۔
قومی نجات کا راستہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، اس میں اس ماں کے آنسو بھی شامل ہیں جو سیاست کو، تہذیب کو، بقاء کی جنگ کو ان معنوں میں نہیں جانتا، جو ہمارے ہاں معروف ہوتا ہے۔
اس جدوجہد میں گمنام لوگوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آرکسٹرا میں شامل ہوتے ہیں، جو اپنی سنگیت سے نغمے کے خدوخال کو بناتے اور ابھارتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں جانکاری کم ہوتی ہے۔
ایک عظیم نغمے کی تخلیق میں دیکھا جائے تو زمانوں کے زمانے لگ جاتے ہیں، تب کوئی لافانی گیت جنم لیتا ہے۔اس لافانی گیت کو خوشبو کی طرح سنبھال کر رکھنے میں ان تمام فن کاروں کا یکساں حصہ ہوتا ہے جو نامور بھی ہوتے ہیں اور گم نام بھی۔ لیکن ہمارے معاشرے کا تو کیا ہی کہنا۔ ہم نے اپنے نجات دہندوں کو ان کی زندگی میں بھی تسلیم نہیں کیا، ان کے کام میں کیڑے ڈالتے رہے۔لیکن جب یہی نجات دہندہ دنیا کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو ہوش و ذہن رکھنے والوں کو ایک نہ ختم ہونے والا خلاء کا احساس ہوا۔ ایسے نایاب لوگ تو روز روز نہیں پیدا ہوتے، مانا کہ حالات اور ماحول ان کی پرداخت میں حصہ لیتے ہیں لیکن ناموافق حالات اور ماحول ان کو کامیاب ہونے سے روکتا بھی تو ہے۔
کیا بلوچوں کیلئے یہ کم ہے کہ ایک آواز نے ان کو حوصلہ بخشا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اس فریب کو توڑا، اس خوف کو زائل کیا جو حکمران اپنے دانش وروں کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی عادت سے بھی تو مجبور ہیں کہ ہمارے ہاں ہر شخص کے اپنے پیمانے ہیں، جو اس کی ذات، اس کی سوچ، امنگوں اور خواہشات کے تابع ہوتا ہے، یہ کیڑے نکالنے والے دیانت دار کم ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارا تاریخی المیہ رہا ہے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو برداشت ہی نہیں کیا، ان کی زندگی کی ایک رخ کو دیکھا اور فیصلہ کر دیا۔ اور پھر اپنی فتوی بیچ چوراہے ٹانک دیا، اب ایسا بھی نہیں کہ بلوچوں نے سردار عطااللہ مینگل سے محبت نہیں کی، بے پناہ محبت کا اظہار کیا (چند نیم خواندہ پڑھے لکھے لوگوں کو چھوڑ کر) وہ بلوچ قوم کا جیتا جاگتا استعارہ بن چکے تھے، وہ مزاحمت کی جیتی جاگتی علامت تھے۔ جب وہ داستان گو کی منصب پر آتے تو بلوچ قوم کے رزمیہ کا ہر ایک پہلو پھول اور آگ ایک دوسرے میں ڈھل جاتے۔ لہجہ کبھی شیریں ہوتا، کبھی اس کا جوش الاؤ بن جاتا، ہر جملہ اپنی جگہ دل میں عجیب و غریب کیفیات کو جنم دیتا۔ جس طرح کافکا نے کہا تھا کہ ادب تو وہی ہے جو ہتھوڑا بن کر ذہن پر برسے۔
سردار عطاء اللہ مینگل کی تقریر اور گفتگو بند دماغوں پر بھی ہتھوڑے کی ضرب لگاتا محسوس ہوتا۔اسی سے تو خوف زدہ ہوکر اسلام آباد نے فیصلہ کیا کہ نیپ کی حکومت کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر سردار عطاء اللہ مینگل کی جگہ کوئی اور وزیر اعلی ہوتا تو شاید ہماری آج کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یا نیپ کو پانچ سال مل جاتے، تب بھی بہت کچھ بدل جاتا۔
اسلام آاباد اس عظیم رزمیہ گو کے سامنے اعصابی طور پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ سردار مینگل کی شخصیت بھٹو کے نام نہاد سحر کو چٹکی بھر میں اڑا دیتا۔ اور بھٹو کا زعم زخم بن کر اس کو چوٹ لگاتا۔ اسی لیئے اسلام آباد اور بھٹو کے گٹھ جوڑ نے نیپ حکومت کا خاتمہ کیا۔ لیکن یہیں سے پھر ایک نئے رزمیہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کے ہیروز پر نظر ڈالی جائے تو انسان حیرت سے پتھر کا بن جائے۔کیا ایسے بھی لوگ بھی ہماری قوم میں تھے، جہنوں نے زندگی کا نذرانے ہنستے مسکراتے دیا، جیسے زندگی کا نذرانہ نہ ہو، کوئی گواڑخ ہو جسے وہ اپنے محبوب پر دان کر دیتا ہے۔یہ آج کی تاریخ ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے بن رہی ہے۔ ایک عظیم المیہ ہے جو پورے بلوچ وطن پر اپنے پ ر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس سے کوئی گھر، گلی، گدان، محل نہیں بچا، اس کی زد میں ماں، بہن، بھائی، بیٹے، پیر وجوان، بچے سبھی آئے ہوئے ہیں۔
یہ رزمیہ کب تک جاری رہے گا؟ کوئی نہیں جانتا۔ گواڑخ کی طرح زندگی کو نذرانے دینے والے اور بہت سے آئیں گے لیکن اگر نہیں آئے گی وہ آواز جو ہمارے داستان گو کی تھی، جو اپنی ساری متاع لے کر جا چکا ہے۔
اب ان بوڑھی آنکھوں کا انتظار ختم ہو چکا ہے، جو اپنے اسد کی قبر کی آس لئے چلا گیا۔ اب وہ وہاں ملیں گے، جہاں پھول ہی پھو ل ہونگے، گواڑخوں کی بہار میں یہ ملاقات بھی کتنی عجیب ہوگی، جسے بیان کرنا مشکل ہے۔ فرط محبت اور شدت غم سے وہ پوچھے گا بیٹا میرے لخت جگر جب تم اور تمھارا دوست احمد شاہ بلخ شیر مزاری کی طرف جا رہے تھے، تو کیا ہوا تھا، مجھے سب بتاؤ، اور تمھیں کہاں چوٹ لگی، ظالموں نے کیسے وار کیا؟ لیکن گواڑخوں کی اس مجلس میں ہمارا یہ مغنی پھر ایک نئے آب سے دوچار ہوگا، اس لئے کہ اس کے شیر جیسے بیٹوں پر آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اسد اور اس کے دوست کے ساتھ ہوا۔
اسد کے بعد شہید نواب اکبر بگٹی کے جانشیں بیٹے کو دن دہاڑے گولیاں مار کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ روایت ہے کہ شہید نواب اکبر بگٹی نے اس کی داڑھی کے دو بال سنبھال رکھے تھے۔ پھر یہی عمل بالاچ مری کے ساتھ ہوا، ان کی زندگی کا چراغ کیسے، کب اور کہاں گل ہوا۔ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہی بابا مری کو معلوم تھا، بلوچوں کے ان تین ہیروز کی کہانی میں یہاں ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔
جب بابا مری نے بالاچ مری کی شہادت پر کہا تھا۔۔۔ لمبی جدائی!
بلوچوں کے رزمیہ کا سب سے بڑاکربناک عنصر صرف ایک ہی ہے۔۔۔۔
لمبی جدائی!
دی بلوچستان پوسٹ: اس تحریر میں پیش کیئے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کے پالیسیوں کا اظہار ہیں