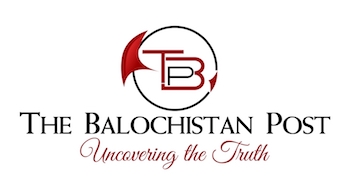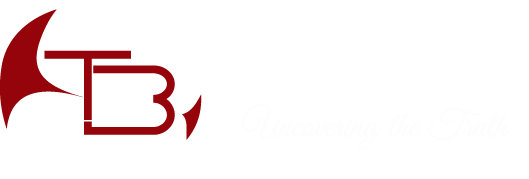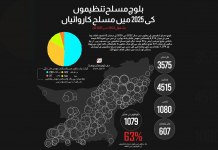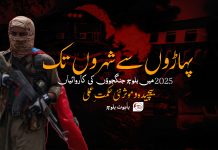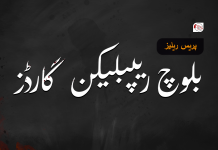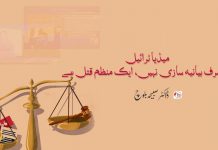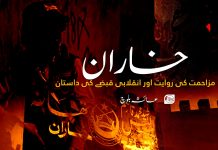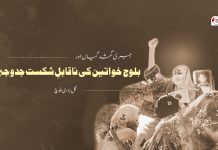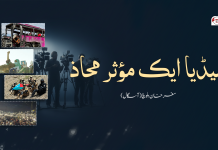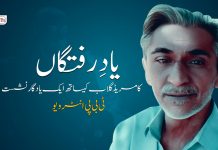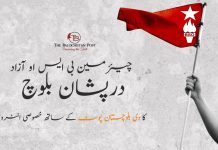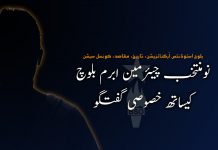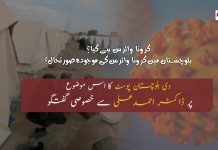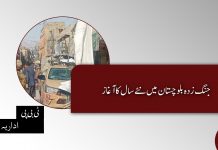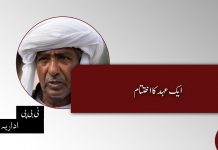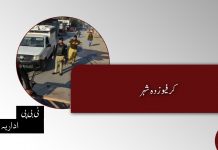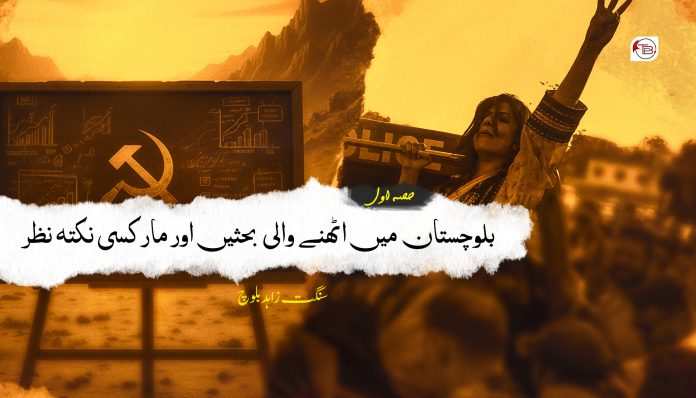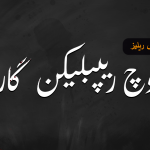بلوچستان میں اٹھنے والی بحثیں اور مارکسی نکتہ نظر (حصہ اول)
تحریر: سنگت زاہد
دی بلوچستان پوسٹ
بلوچستان کی تحریک میرے دل کے بہت قریب ہے کہ اس نے میرے لیے ایک استاد کا کردار ادا کیا ہے۔ آج کے زمانے میں مارکسی طالب علموں کی ایک مشکل یہ رہی ہے کہ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو ہمارے علاقوں میں کوئی توانا مارکسی تحریکیں موجود ہی نہ تھیں جبکہ ہمارے پاس جو علم پہنچتا ہے وہ معاشرے میں شدید تضادات کی روشنی میں لکھا گیا ہوتا ہے جہاں انقلابی تحریکیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور ریاست سے نبردآزما دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے میں ان کلاسیکی تحریروں کو پڑھنا تو آسان ہوتا ہے مگر سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسے میں بلوچ قوم کی تحریک میں ایسے بہت سارے عوامل دکھائی دیتے ہیں جو یہ سمجھنے میں آسانی پیدا کرتے ہیں کہ ماؤ فینن، چی گویرا اور دیگر انقلابیوں نے جو تحریر کیا اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میری نظریاتی تربیت میں بھی بلوچستان کی تحریک کا انتہائی اہم کردار ہے باوجود اس کے کہ میں کبھی اسے کچھ نہ دے سکا۔
بات نکلی ہے تو یہاں یہ بھی اعتراف کرتا چلوں کہ جب ہم دوستوں نے این ایس ایف میں سیاست کا آغاز کیا تو ہم چین کی روش سے پریشان تو ضرور تھے مگر اس پر کوئی تنقید قائم نہ کر سکے تھے اور ڈینگ سے لے کر موجودہ چین کو ماؤ کے تسلسل کے طور پر ہی دیکھتے تھے۔ بلوچستان کی بدولت ہی ہم چین کے سوشل سامراجی کردار کو دیکھ سکے اور پھر ہمیں موقع ملا کہ چین کی ماضی میں ہونے والی پارٹی کے اندر کی لڑائیوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیں جس نے ہمیں ڈینگ ازم کے دلدل سے نجات دلائی۔ یہی وجہ ہے کہ کوشش رہتی ہے کہ نہ صرف بلوچستان کی تحریک پر نظر رہے بلکہ وہاں اٹھنے والے بحث و مباحثوں کو بھی پڑھا جائے۔
حالیہ دنوں میں ایسی ہی ایک بحث پڑھنے کا اتفاق ہوا جہاں بہت سے ایسے اہم موضوعات کا ذکر تھا جو کسی بھی تنظیم یا تحریک سے وابستہ افراد کے لیے انتہائی اہم تھے جیسے تنقید اور خود تنقیدی، علم اور عمل، فرد، طبقات، عوام اور قوم، حب الوطنی اور قومی آزادی، نظریہ اور عملی حکمت عملی اور پھر تاریخ میں فرد کے کردار اور چین کے ثقافتی انقلاب پر بھی گفتگو کی گئی۔ مگر گفتگو اس انداز میں تھی کہ سب کچھ ہر ایک کی سمجھ میں آنا مشکل تھا اور چونکہ یہ ایک مکالمہ تھا تو بہت وضاحت کے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو نہ ہوئی جس کی وجہ سے ایک عام شخص کے لیے ان موضوعات کو گہرائی میں سمجھنا مشکل تھا۔ چونکہ میں بھی بہت سے ایسے پہلوؤں سے ناواقف ہوں جن کے پیرائے میں یہ گفتگو کی گئی اور نہ میں تحریری یا عملی حوالے سے تحریک میں حصہ دار ہوں لہٰذا کون صحیح اور کون غلط ہے اس کا تعین نہ میں کر سکتا ہوں نہ مجھے کرنا چاہیے۔ پھر بھی یہ تحریر رقم کرنے کا مقصد خود ان موضوعات کو مارکسی نکتہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور ایک عام کارکن تک چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو ان موضوعات کو پہنچانا ہے کیونکہ انہیں سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میں خود کوئی مفکر نہیں بلکہ ایک سیاسی طالب علم ہوں لہٰذا جواب میں اگر کوئی تنقیدی تحریر لکھتا ہے تو اسے مثبت انداز میں لیتے ہوئے اپنی اصلاح کا موقع سمجھوں گا۔
تاریخ میں فرد کا کردار
“انسان اپنی تاریخ خود تخلیق کرتا ہے مگر ویسے نہیں کہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے حالات کے مطابق تاریخ تخلیق نہیں کر سکتا بلکہ ان معروضی حالات کے مطابق جو موجود ہیں اور اس کو تاریخ سے ملے ہیں۔” کارل مارکس، ۱۸ برومائر
یہ موضوع ویسے تو یورپ میں سرمایہ داری اور قوم کے سوال کے ساتھ ہی جنم لے چکا تھا اور کانٹ سے لے کر ہیگل تک تمام جرمن فلسفی اس ہی سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس کی وجہ شہرت روسی مارکسی فلسفی پلیخانوف کی اسی نام سے لکھی جانے والی کتاب بنی جس میں انہوں نے زار کے خلاف عمل پیرا ایک گروہ جو نارودنک کہلاتے تھے ان کے “ہیرو” کے تصور کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ نارودنک نظریے کا ماننا یہ تھا کہ تاریخ کو آگے بڑھانے میں چند تنقیدی سوچ رکھنے والے لوگ ہی کردار ادا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے ہیرو قرار دیا جو باقی انسانوں سے ممتاز اور اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ عوام کے پاس کوئی تنقیدی و تخلیقی صلاحیت نہیں ہوتی اور ہیروز انہیں جہاں بھی لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارودنک گروہ عوام سے جڑے بغیر بس اپنے طور پر زار پر مختلف حملے کرتے رہتے تھے۔
پلیخانوف کا ماننا تھا کہ چند انسان تاریخ نہیں بناتے بلکہ یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی اجتماعی تخلیقی صلاحیتوں سے بنتی ہے جس میں مختلف طبقات کا مختلف کردار ہوتا ہے اور سماجی، معاشی اور مادی حالات اس کا تعین کرتے ہیں کہ کب کن طبقات کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پلیخانوف لکھتے ہیں کہ “محنت کشوں کی مستقل تیزی سے بڑھتی ہوئی طبقاتی جدوجہد مختلف ریفارمرز کے خیالی منصوبوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا تعین کرنے میں مروجہ پیداواری اور تجارتی اصول کارفرما ہیں۔” لہٰذا کوئی بھی فرد ان معاشی و سماجی حالات کے اندر رہتے ہوئے ہی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر فرد کو تاریخ پر اثر انداز ہونا ہے تو اس کو اپنے حالات کا بہترین تجزیہ کرنا ہوگا اور ایسے طبقے اور عوام کے ساتھ جڑ کر اپنی صلاحیتوں کو ان کی تحریکوں میں استعمال کرنا ہوگا جو ان حالات میں اہم ہیں کیونکہ وہی تبدیلی لا سکتے ہیں۔
لینن اور موضوعی ارادیت
ابتدائی طور پر لینن نے پلیخانوف کی نارودنک نظریے پر تنقید کا خیر مقدم کیا لیکن ۱۹۰۵ تک لینن کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر نارودنک ایک انتہا پر پھنسے ہیں تو پلیخانوف اور منشویک دوسری انتہا پر ہیں کیونکہ انہوں نے بجائے کچھ ٹھوس عملی اقدام کرنے کے اپنا کام محض طبقاتی تجزیے کو محنت کشوں میں لے کر جانا بنایا ہوا ہے اور محنت کش طبقہ کسی انقلابی سرگرمی کے بجائے محض اپنی روزمرہ کی آٹھ آنے چار آنے کی ٹریڈ یونین کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ لینن کا کہنا تھا کہ فرد یاموضوعی ارادیت (Subjective Will) اور معروضی حالات (Objective Conditions) میں سے کسی ایک کو چننا جدلیاتی فکر کی عکاسی نہیں کرتا بلکہ ہمیں ان دونوں کی جدلیات کو سمجھنا ہوگا کیونکہ مارکسزم ایک عملی نظریہ ہے۔ ایک طرح سے ماضی میں مارکس نے بھی یہی کہا تھا کہ “فلسفیوں نے دنیا کی تشریح کی ہے مگر اصل کام اس کو تبدیل کرنا ہے۔”
لینن کا ماننا تھا کہ محنت کشوں میں طبقاتی شعور تو ضرور موجود ہوتا ہے یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ طبقاتی بنیاد پر زیادتی ہو رہی ہے لیکن ان کے پاس وہ مواقع موجود نہیں ہوتے کہ وہ پڑھ سکیں اور ایک باقاعدہ انداز میں تجزیہ قائم کر سکیں لہٰذا ان کے اندر انقلابی شعور پیدا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے پیشہ ورانہ انقلابیوں کی ایک پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جسے اس نے انقلاب کا ہراول دستہ (Vanguard) قرار دیا۔ آج جو کیڈر پارٹی کا تصور پایا جاتا ہے وہ لینن ہی کے ذریعے تعمیر ہوا جس کے بغیر کسی طرح کا کوئی انقلاب ممکن نہیں۔ لیکن لینن کی پیشہ ورانہ انقلابیوں کی پارٹی کا تصور نارودنک کے ہیروز سے مختلف تھا یعنی پارٹی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی بلکہ اس کا کام عوام میں جانا اور انہیں انقلاب کے لیے تیار کرنا تھا اور اس کے ذریعے ہی انقلاب برپا کرنا تھا۔ پارٹی خود محنت کش طبقے کی نمائندہ تھی اس سے علیحدہ کوئی شے نہ تھی۔ لینن کے اس تصور کے بغیر نہ صرف روس کا انقلاب بلکہ اس کے بعد پوری دنیا میں آنے والے مختلف انقلابات ممکن نہ تھے۔
ماؤ اور عوامی لائن
اگر لینن نے یہ جدلیاتی رشتہ دریافت نہ کیا ہوتا تو ماؤ کے لیے ایک ایسے معاشرے میں جہاں سرمایہ داری اور محنت کش طبقہ نہ ہونے کے برابر تھا شاید انقلابی راستہ نکالنا ہی مشکل ہوتا کیونکہ مارکسزم تو پیدا ہی سرمایہ دارانہ نظام کے بعد سرمایہ داری کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے اور صنعتی مزدور کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کے لیے ہوا تھا۔ یہ ماؤ کی موضوعی ارادیت ہی تھی جس نے کالونیل اور جاگیردارانہ سماج میں نئی جمہوریت کے ذریعے انقلاب کا راستہ تلاش کیا۔ مگر ماؤ نے اس جدلیاتی رشتے میں ایک اور عمل پر بہت زور دیا جس کو کسی حد تک اسٹالن نے پروان چڑھایا تھا لیکن ماؤ اس کو ایک دائمی اصول بنا دیتا ہے۔ ماؤ کا ماننا یہ تھا کہ درست انقلابی لائن کے لیے نہ صرف لینن کی پیشہ ورانہ پارٹی کو عوام میں انقلابی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ پارٹی کو بھی اپنی انقلابی لائن درست رکھنے کے لیے عوامی لائن (Mass Line) حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
مگر عوامی لائن ہے کیا؟ ماؤ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ “عوام کے خیالات کو لو، انہیں سمیٹو اور واضح کرو، پھر ان خیالات کو عوام کے پاس واپس لے جاؤ، ان پر ثابت قدم رہو اور انہیں عملی جامہ پہناؤ تاکہ قیادت کے درست خیالات تشکیل پائیں — یہی قیادت کا بنیادی طریقہ ہے۔”
ویسے تو عوامی لائن ہر زمانے میں ماؤ کے سیاسی سفر اور انقلابی حکمت عملی کا بنیادی جز رہی مگر ۱۹۵۶ میں خاص طور پر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ماؤ نے اس تصور کو ایک الگ مقام پر پہنچا دیا۔ ۱۹۵۶ میں اسٹالن کا کلٹ توڑنے کے نام پر سوویت یونین میں خروشیف نے ترمیم پسندی کے اس سفر کا آغاز کیا جو گورباچوف کے زمانے میں سوویت یونین کے خاتمے پر ختم ہوا اور اس ہی زمانے میں چین کی کمیونسٹ پارٹی نے یہ طے کیا کہ ملک کو کلٹ سے بچانے کے لیے چین کی پارٹی کی دستاویز میں سے ماؤ زے تنگ فکر کا لفظ حذف کر دیا جائے لیکن اس کا مقصد بھی چین کو ترمیم پسندی کی طرف دھکیلنا تھا۔
دو سطحی جدوجہد
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر جب تنقیدی حملے نظریات کے بجائے ذاتی نوعیت کے ہوں تو ان کا مقصد تنظیم یا تحریک کی اصلاح کرنے سے زیادہ اپنے چند مفادات کا تعاقب ہوتا ہے۔ بہر حال ایسی صورتحال میں ماؤ دو سطحی جدوجہد (Two Line Struggle or Line Struggle) کا تصور سامنے لے کر آتا ہے۔ اس کے مطابق کسی بھی پارٹی یا تحریک یا جدوجہد میں ہمیشہ دو یا اس سے زیادہ سیاسی لائنوں کا ٹکراؤ رہتا ہے اور جن میں سے ایک لائن درست ہوتی ہے اور باقی غلط اور موقع پرست ہوتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر مختلف طبقات موجود ہوتے ہیں جو اپنے نظریات اور مفادات پارٹی میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔
اسی لیے پارٹیوں اور تحریکوں کے اندر جدوجہد ضروری ہوتی ہے اور یہاں ماؤ عوامی لائن کا ایک اور انداز میں استعمال کرتا ہے جہاں عوام کا کام پارٹیوں کی غلط لائن کو درست کرنا بھی بن جاتا ہے۔ مگر پارٹیوں کی لائن درست رکھنے یا اس کو درست کرنے کے عمل کا دارومدار تنقید اور خود تنقیدی کے ساتھ جڑا ہے جس پر اس مضمون کے اگلے حصے میں بات چیت کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی رائے دینا چاہوں گا کہ آیا ماؤ کے ثقافتی انقلاب کا تجربہ ہی غلط تھا یا کوئی اور عوامل اور غلطیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ تجربہ ناکام ہوا۔
شیر محمد مری اور عوامی لائن
ایک سیاسی کارکن کے لیے یہ ساری بحث بے کار ہے اگر اسے کسی ایسے عمل کی روشنی میں نہ دیکھا جائے جس سے ہم کسی نہ کسی صورت جڑے ہوں۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو کیا اس تحریک کو خیر بخش مری و شیر محمد مری اور ان کی بنائی ہوئی تنظیموں اور تعلیمات سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہی بلوچستان کے لینن اور ماؤ ہیں جنہوں نے ایسی تنظیموں کی بنیاد رکھی اور مستقبل کی ایسی تنظیموں کا تصور دیا کہ جن میں پیشہ ور انقلابی عمل پیرا ہوں۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ان تنظیموں اور افراد کو اپنی لائن درست رکھنے یا کرنے کے لیے سبق کیا دیا؟
اس حوالے سے میں شیر محمد مری کے اس انٹرویو کی طرف توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا جو انہوں نے ریاست کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے بعد دیا تھا۔ اس میں وہ اس وقت کے سندھی قوم پرستوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ “چھ لڑکے، چار دانشور اور دو وکیل” مل کر انقلاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ “آپ عوام کے سامنے استاد بن کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو عوام سے سیکھنا چاہیے کیونکہ عوام ہی انقلاب کے بہترین استاد ہیں۔”
اس ہی انٹرویو میں ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپ سرمایہ داروں کی نمائندہ پارٹی تھی جو صرف الفاظ کی حد تک ترقی پسند اور قوم پرست تھی۔ ایک اور مقام پر وہ سندھی قوم پرستوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ “چند جاگیرداروں کی قوم پرستی چاہتے ہیں یا کچلے ہوئے طبقات کی؟” اس کا مطلب ہے کہ شیر محمد مری نہ صرف تحریکوں میں دو سطحی جدوجہد کے قائل تھے بلکہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جدوجہد مختلف طبقات سے آتی ہے۔ نیپ اور بزنجو صاحب اگر لوگوں کو فیڈریشن کی سیاست کی طرف کھینچتے تھے تو اس بات سے سوا کہ اس میں کس طبقے کے لوگ تھے ان کی لائن گماشتہ سرمایہ داروں سے ہی آ رہی تھی جبکہ خیر بخش مری اور شیر محمد مری کے کیمپ کو لاکھ سرداروں کا کیمپ کہا جاتا ہو مگر عوامی لائن کے اطلاق کی وجہ سے ان کی لائن بلوچستان کے پسے ہوئے طبقات سے آ رہی تھی۔
قومی تحریکوں میں مختلف لائنیں کارفرما رہتی ہیں کیونکہ قومی آزادی کے خواہاں مختلف طبقات ہوتے ہیں مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عوامی لائن پر عمل پیرا پارٹیاں اور افراد تمام دیگر تضادات کو اس وقت پس پشت ڈال کر تمام قوتوں کو بنیادی تضاد یعنی قبضہ گیر سامراجی قوت کے خلاف یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف طبقات کے آپس کے تضادات ختم ہو جاتے ہیں مگر درست لائن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ تضادات سامراج کے خلاف لڑائی میں حائل نہ ہوں۔
مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ تنقید پر پہرے بٹھا دیے جائیں؟
۔۔۔۔۔ جاری
دی بلوچستان پوسٹ: اس تحریر میں پیش کیئے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کے پالیسیوں کا اظہار ہیں۔