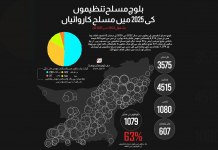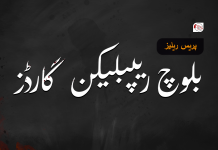بابا جان، استاد تالپور
تحریر: ہزاران رحیم داد
ترجمہ : ساگر بلوچ
دی بلوچستان پوسٹ
بابا جان، استاد تالپور،
میں نے آج پھر آپ کو لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آخری بار میں نے آپ کو مارچ کے آخر میں لکھا تھا، جب ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ (بی وائے سی کی سربراہ اور اُن چند آواز میں سے ایک جو ہمارے ضمیر کو اجتماعی طور پر زندہ رکھی ہوئی ہے) کو حراست میں لیا گیا تھا۔ آج میں آپ کو دوبارہ لکھ رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے وجہ ضرور پہلے ہی محسوس کی ہوگی۔ ایسے بھاری کٹھن لمحوں میں، جب آپکی طرف رجوع کرتی ہوں تو اس لیے نہیں کہ آپ ہر جواب دینے کا وعدہ کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کبھی سوالوں سے منھ نہیں موڑتے۔
میں آج آپ کو صرف ایک لکھاری کی صورت میں یا محض بلوچ معاشرے کی ایک فرد کے طور پر نہیں لکھ رہی بلکہ میں ایک عورت کی حیثیت سے، ایک ایسی صورتِ حال کے ردِعمل میں جو ہر صاحبِ ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، خواہ اس کی قومیت ذات عقیدہ کچھ بھی ہو یا کتنا ہی جانبداری کے حصار میں محفوظ ہو۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب شناخت، جو کچھ سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کے بوجھ تلے دب کر بکھر جاتی ہے، اور خاموشی خود ایک مؤقف بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ ہے۔
بابا جان، “لاپتہ”، یا “بیگواہ” یا “جبری گمشدگی” جیسے الفاظ اب ہمارے درمیان افسوس ناک حد تک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاحات بن چکے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ ہے وہ کل پوسٹر بن چکا ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر یہ حقیقت ہے۔ اب چہرے اور تعداد اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کس کو پوسٹ کرنا ہے اور بعض اوقات جن لوگوں کے نام ہم نہیں لیتے، جنہیں ہم یاد نہیں رکھتے یا نہیں پھیلاتے یہی کثرت احساسِ جرم کو جنم دیتی ہے۔ مگر یہ بھی جبری گمشدگی کے عمل کا حصہ ہے جو اب معمول بن چکی ہے۔
اب ہم دستکوں کی آواز سے بوٹوں کی چاپ سے، گھسیٹے گئے قدموں سے مانوس ہو چکے ہیں، اس لمحے سے مانوس ہو چکے ہیں جب فورسز ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے کسی عزیر کو اٹھاتے ہیں اور ہمیں زبردستی یہ سب دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مردوں کو اٹھایا جاتا ہے اور عورتوں کو اس درد کے ساتھ جیے جانے کے لیے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔
میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گی۔ ایک ہی کافی ہے۔ ہم سمی کے بارے میں سنتے ہیں، ہم اس کے لاپتہ والد ڈاکٹر دین محمد کو جانتے ہیں۔ یوں شناختیں عدم موجودگی سے اور زندگیاں رشتوں کی حاشیہ نویسی میں سمیٹ کر نئی شکل اختیار کرتی ہیں۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میں یہ سب صرف ایک گواہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عورت کے طور پر لکھنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ اب ہمارے سامنے خود بلوچ عورتوں کی جبری گمشدگیوں کی شدّت ہے۔
بابا جان، عورتوں کے طور پر ہم نے خوف کے روزمرہ کے ہر لہجے کو سیکھ لیا ہے۔ کراچی، کوئٹہ یا کسی بھی شہر میں، جب ہم باہر نکلتی ہیں تو ہمیں گُھورا جاتا ہے، پیچھا کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر ٹکرایا جاتا ہے، اور کبھی ہاتھ بھی ڈالا جاتا ہے۔ ہم فطری طور پر ردِعمل کرنا سیکھ لیتی ہیں، نظرانداز کرنا، چیخنا، ضرورت پڑنے پر پلٹ کر تھپڑ مارنا۔ کبھی محض کسی بھیڑ بھری سڑک پر ایک طویل گھورتی نظر سے، جسم تن جاتا ہے، تحفظ کا احساس ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر وہ خوف عارضی ہوتا ہے، ہم اپنے پر اختیار رکھتی ہیں۔ کم از کم نظری طور پر، ہمارے پاس مزاحمت کی طاقت باقی رہتی ہے۔
اب ذرا کچھ اور تصور کریں۔ تصور کریں کہ آپ کو زبردستی اٹھا لیا جائے۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی وارنٹ، نہ کوئی منزل، نہ یہ معلوم کہ آپ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسا خوف تصور کریں جس کی کوئی مدت نہ ہو، کوئی اختتام نہ ہو۔ مکمل بے اختیاری کا تصور کریں۔ غم، اندھیرے اور تڑپ کا تصور کریں۔
اب جبری گمشدگی صرف بلوچ مردوں تک محدود نہیں رہی یہ ریاستی قوتیں اب عورتوں کے لیے بھی آ رہی ہیں۔ جنکے ٹھکانے نامعلوم اور ان کی تقدیر بے زبان ہیں۔ مجھے یاد ہے 2022 میں جب دو بچوں کی ماں حبیہ کو کراچی سے جبری طور پر غائب کیا گیا اور بعد میں رہا کر دیا گیا۔ پھر ماھل بلوچ، دو بچوں کی ماں، کوئٹہ سے اٹھائی گئی، بعد میں رہا ہوئیں، اور اب 2025 تک یہ ایک سخت پیٹرن بن چکا ہے۔ بہت سے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور کہیں کبھی رپورٹ ہوتے ہی نہیں۔ ماہ جبین پولیو کی مریضہ ہے، ھانی آٹھ ماہ کی حاملہ ہے۔ نسرین سترہ برس کی ہے اور ہیرالنسا بھی۔ رحیمہ اب تک لاپتہ ہے۔ آخر کوئی کس طرح اتنی اذیت ناک حد تک غائب ہو سکتا ہے۔
یہ خیال ناقابلِ برداشت ہے جب میں ان کی بے بسی اور مکمل بے اختیاری کے بارے میں سوچتی ہوں۔ مہینے گزر چکے ہیں، مگر ماہ جبین کا انجام آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ بے جواب سوال ہر چیز کو اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔ بعض اوقات یہ میرے اندر، ایک عورت ہونے کے ناتے، ایک لکھاری ہونے کے ناتے، شدید احساسِ جرم پیدا کرتا ہے۔
کیا ہم نے ماہ جبین کے حوالے سے بہت کم بات کی؟
کیا ہم نے کافی زور سے اور کافی دیر تک آواز نہ اٹھا کر اس کے ساتھ ناانصافی کی؟
ہم اسے واپس کیوں نہ لاسکے؟
اس کے ساتھ کیا ہوا؟
وہ اس وقت کہاں ہے؟
کیا وہ زندہ ہے؟
کیا اس پر تشدد کی جا رہی ہے جو وہ برداشت بھی نہ کر سکے؟ یا شاید اس سے بھی بدتر ہو۔
اس نے اس جگہ کیا کچھ سہا ہوگا جو اس کے وجود کو تسلیم تک نہیں کرتی، جہاں کسی جیل کے ریکارڈ میں اس کا نام تک درج نہیں؟
میں یہاں “تشدد” کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی رہا ہوا واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے جسم دیکھے ہیں، کچھ بول پاتے ہیں، کچھ وہ کہانیاں عمر بھر اپنے سینے میں دفن کیے رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک زندہ بچ جانے والے نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ اُن کوٹھڑیوں کے اندر، تم انسان نہیں رہتے۔
ایک پائپ منہ میں ٹھونس دیا جاتا ہے اور دو اہلکار پیٹ پر بیٹھ کر جسم پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر پانی ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ زندگی خود ایک سودے کی طرح لگنے لگتی ہے۔
پھر جسم کو گھسیٹ کر باہر لایا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور تفتیشی افسر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔
ایک سوال پوچھا جاتا ہے۔
صرف ہاں یا ناں۔
وہ ہاتھ میں انجیکشن لیے انتظار کرتا ہے، کہ کہیں روح جسم سے نکل نہ جائے۔
میں انسان کے نام پر انسانیت کھو دیتی ہوں۔
میں اس سے آگے کچھ بیان نہیں کروں گی۔
میں مانتی ہوں کہ زبان میں بھی کچھ حدیں ہونی چاہئیں۔
میرے ہاتھ اس سے پہلے جل جائیں کہ میں اس “ظلم” کو مکمل طور پر قلم بند کروں جو لوگ ہم پر اس وقت امانت رکھتے ہیں جب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔
بابا جان، اب جب کے عورتوں کو بھی لاپتہ کیا جا رہا ہے، تو ہماری سوچ کی حدیں بھی آزمائی جا رہی ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہی لاعلمی بذاتِ خود ایک تشدد ہے۔ شروع میں صرف ماہ جبین تھی اب کئی نام ہیں، ہم بولتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں تو پھر ایک اور عورت غائب ہو جاتی ہے۔
آپ دوبارہ بولتے ہیں، دوبارہ لکھتے ہیں، دوبارہ غم مناتے ہیں، اور پھر ایک اور نام سامنے آ جاتا ہے۔
چہرے بدل جاتے ہیں۔
نام بدل جاتے ہیں۔
جو چیز نہیں بدلتی تو وہ یہی مشینری ہے۔
یوں ہی 2009 میں بلوچ مردوں کی گمشدگی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک ایک کرکے کیسز فہرست اتنی طویل ہو گئی کہ یادداشت بھی ساتھ نہ دے سکی۔
شروع میں تو لوگ رپورٹ کرتے ہیں مگر پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ تشدد ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنا جاری رہتا ہے کہ معمول بن جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد، لاپتہ ہونا زندگی کی ایک حقیقت بن جاتا ہے۔ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور دنیا آگے بڑھ جاتی ہے۔ بلوچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اور پھر میڈیا سے بھی غائب کر دیے جاتے ہیں۔ نیوز چینلز خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور آزاد صحافی ذاتی خطرات کے باوجود بمشکل ہی رپورٹ کرتے ہیں۔ مقامی لکھنے والوں کو جانبدار کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے، یا انہیں بالکل نہ لکھنے کی تنبیہ کی جاتی ہے۔
بابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ عالمی و قومی تحریکیں عورتوں کے حقوق، بااختیار بنانے، جسمانی خودمختاری، تعلیم اور ڈیجیٹل تحفظ پر بھرپور آواز اٹھا رہی ہیں۔ یہ سب جدوجہد اہم ہیں۔ لیکن بلوچ عورتیں بھی تو عورتیں ہیں۔ کسی عورت کا لاپتہ ہونا ہر عورت کو جھنجھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ذات، قوم یا ملک سے ہو۔ کسی انسان کا غائب ہو جانا ہر ضمیر کو بے چین کر دینا چاہیے۔ مگر پھر بھی، آٹھ ماہ کی حاملہ عورت کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور دنیا کانپتی تک نہیں۔
میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ بلوچ عورتوں کو جبراً لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ سب “معمول” بنتا جا رہا ہے، یا شاید اس سے بھی بدتر ابھی آنا باقی ہے؟ کیا ہم وہ جانور ہیں، جیسا کہ اورویل نے کہا تھا، جو دوسروں کے مقابلے میں کم برابر ہیں؟
دی بلوچستان پوسٹ: اس تحریر میں پیش کیئے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کے پالیسیوں کا اظہار ہیں۔