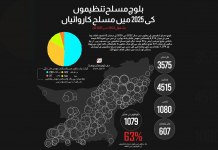تاریخی کہانیاں
تحریر: ابراہیم بلوچ
دی بلوچستان پوسٹ
1: جنت پہ قبضے کی کہانی
ایک وقت تھا جب یہ سبز وادیاں خوشیوں کی آغوش میں بستی تھیں۔ مٹی کی خوشبو، بہتی ندیوں کا سرگوشی بھرنا، اور پہاڑوں کی چوٹیاں جیسے آسمان کو چھونے کی کوشش میں تھیں، تمام قدرتی تحائف سے مالامال دھرتی جو چار موسموں کی خاصیت اور سینکڑوں میل طویل ساحل کے ساتھ سونے کی چڑیا کے نام سے جانی جاتی ہے اپنی ہزاروں سالہ تاریخ، ثقافت اور محبت کی کہانیوں کا خزانہ تھی، جو نسل در نسل منتقل ہوتی آرہی تھیں۔۔
سردیوں کی شامیں جب برف کی چادر چڑھاتی تھیں تو یہ منظر حقیقی جنت کا سا لگتا۔
لیکن ایک دن، ہوا کا رخ بدل گیا۔ باہر سے آئے نوآبادکاروں نے اس جنت پر قدم رکھا، جیسے آندھی کے ساتھ طوفان آتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں طاقت کی چمک اور دلوں میں لالچ کی آگ تھی۔ یہ نوآبادکار صرف زمین کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ جبر، سامراجی سوچ، اور بے ظرف ثقافت کا طوفان بھی لائے۔
جب بھی ان کی نظریں مقامی لوگوں پر پڑتیں، وہ حقارت سے اور فاتحانہ انداز میں پیش آتے، کیونکہ وہ دھوکے سے قابض ہو چکے تھے۔ مقامی لوگ ایک ناقابلِ برداشت حقیقت کا سامنا کر رہے تھے: ان کی ثقافت، روایات، اور زمین سب کچھ خطرے میں تھا۔
جیسے ہی نوآبادکاروں نے زمین پر قدم رکھا، وادیوں کی خوبصورتی تاریکی میں ڈھلنے لگی۔ زمین کی گود میں خوشبو اور سرگوشیاں اب خوف کی خاموشی میں تبدیل ہو گئیں۔ مقامی لوگوں کے دلوں میں ایک سوال ابھرا:
“کیا ہم اپنی جڑوں کو کُھو دیں گے؟”
یہ سوال ایک زہر کی طرح پھیلتا گیا، جو لوگوں کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔
ایسے وقت میں، کچھ نوجوانوں نے پہاڑوں کو اپنی کمین گاہوں میں تبدیل کر لیا، کیونکہ اب شہر ان کے لیے محفوظ نہیں رہے تھے۔ جہاں انہوں نے خوشگوار بچپن گزارا تھا، وہاں اب خوف کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ جیسے فلسفی جان ژاک روسو نے کہا،
“انسان کو آزاد پیدا کیا گیا، لیکن ہر جگہ زنجیروں میں ہے” کے مصداق، آزادی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہاڑوں کی خاموشی اور سکون نے انہیں ایک نئی امید دی۔
کیا یہ پہاڑ ان کے لئے ایک نئی جنت بن سکتے تھے؟
یہ سوال ان کی روحوں میں گونج رہا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ سوچ تھی کہ شاید قدرت کی آغوش میں وہ اپنی ثقافت کی گہرائیوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں سر کرنے لگے، انہیں ایک نئی زندگی کی جھلک ملنے لگی۔
زمین کی قدریں دھوکہ دہی کے سامنے بے بسی کی علامت بن گئیں، ایک گہرے درد کا آغاز ہوا۔ نوآبادکار کی طاقت نے مقامی لوگوں کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ کیونکہ وہ انکی تاریخی شناخت اور مزاحمت سے واقفیت رکھتا تھا یہ صرف زمین کا قبضہ نہیں تھا؛ یہ ایک پوری تہذیب کی نسل کشی کی داستان تھی۔
لیکن اس اندھیری رات کے سائے میں، ایک روشنی کی کرن موجود تھی۔ مقامی لوگوں کی امید کی چنگاری، جو ان کی ثقافت کی طاقت سے بھری ہوئی تھی، اب بھی زندہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، بلکہ ان کی شناخت اور بقاء کی ہے۔
اسی طرح، نوجوانوں کی پہاڑوں میں کمین گاہوں نے انہیں یہ سبق سکھایا کہ
“حقیقی آزادی انسان کی اپنی ثقافت میں ہوتی ہے”، جیسا کہ ہنری ڈیوڈ تھور نے کہا۔ جہاں خوابوں کو چور چور کیا جا رہا تھا، لوگوں نے عزم کیا کہ وہ اپنی ثقافت کے لئے لڑیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زمین کی خوشبو، محبت، اور روایات ہمیشہ ان کے دلوں میں بسی رہیں گی۔
یہی وہ لمحہ تھا جب امید کی روشنی نے عزم کی شمع روشن کی، اور مقامی لوگوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جدوجہد ایک نئی صبح کی شروعات ہوگی، جہاں وہ اپنی
جڑوں کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے حق کے لئے لڑیں گے۔
2: تاریخی شناخت کے انکار اور خونریز فوج کشی کی کہانی۔
نوآبادکارں کی آمد ایک تہذیب کے زوال کا آغاز تھی۔ جب وہ اس سرزمین پر اترے، تو ان کی آنکھوں میں جو طاقت کی چمک تھی، وہ مقامی لوگوں کی روحوں میں بکھرے خوابوں کی چمک کو چُرانے کے لیے کافی تھی۔ زمین کی خوشبو، جو کئی نسلوں کی محنت و مشقت کی عکاسی کرتی تھی، اب ایک نئے مہلک عہد کی آہٹ محسوس کر رہی تھی۔
نوآبادکاروں نے آتے ہی مقامی لوگوں کی ثقافت کو دبا دیا۔ زبانیں جن میں محبت، جنگ، اور حیات کی کہانیاں تھیں، ایک ایک کر کے خاموش ہونے لگیں۔ رسم و رواج کی گونج، جو کبھی گاؤں کے چوراہے پر خوشیوں کی محفل سجاتی تھی، اب خوف کے سائے میں دب گئی۔ یہ ایک ایسا ثقافتی قتل تھا جس نے ایک نسل کی تاریخ کو مٹا دیا۔
ایک شام، جب گاؤں کے لوگ اپنی روایتی محفل سجا رہے تھے، ان کی مسکراہٹیں اور قہقہے ایک خاموش نغمے کی مانند تھے۔ اچانک، نوآبادکار فوجی آ دھمکے۔ انہوں نے نہ صرف جانیں لی بلکہ ان کی روحوں کو بھی داغدار کر دیا۔ بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کا خون زمین پر بہتا رہا، جیسے زمین کی گود سے نکلی ہوئی خوشیاں اب خاک میں مل گئی ہوں۔
اس لمحے ایک نوجوان لڑکاجو اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں، جیسے اس نے زندگی کی تلخیوں کو پہلی بار محسوس کیا ہو۔
وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کہ سوال کررہا تھا جسنے اسکا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا کہ کوئی حرکت نہ کرے نہیں تو مارا جاے گا:
“ہماری شناخت کا کیا ہوگا؟”
لیکن اس کے باپ کی آنکھیں جواب دینے سے قاصر تھیں، کیونکہ انہوں نے خود کو طاقت کے سامنے بے بس پایا۔
نوآبادکار کے ظلم نے ایک نئے فلسفیانہ سوال کو جنم دیا۔
“کیا ثقافت صرف ایک وجود ہے، یا یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے؟” جیسے ہی گاؤں کے لوگ اپنے شہیدوں کی یاد میں آنکھیں بند کرتے، وہ اپنے ماضی کی خوشبو کو کھو دینے کا احساس کرتے۔ ان کی خاموشی میں ایک درد تھا، ایک ایسی خاموشی جو نہ صرف ان کے جسموں کو بلکہ ان کی روحوں کو بھی ٹوٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔
کیا یہ صرف ایک زمین کا قبضہ تھا، یا یہ انسانی روحوں کی نسل کشی تھی؟ جب ایک قوم اپنی ثقافت کو کھو دیتی ہے، تو وہ اپنے وجود کی بنیاد کو بھی کھو دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مقامی لوگوں نے احساس کیا کہ ان کی زبانیں، ان کی کہانیاں، اور ان کی روایات ایک جبر کی گہرائی میں دھنس رہی ہیں۔ وہ جان گئے کہ یہ ایک جنگ ہے، ایک جنگ جو صرف زمین کے لیے نہیں، بلکہ ان کی شناخت کے لیے بھی لڑنی ہے۔
یہ ایک ایسی کھلی نسل کُشی تھی جو صرف جسموں کا نہیں، بلکہ روحوں کا بھی قتل کر رہی تھی۔ اس لمحے کی گونج، نہ صرف زمین کے کونے کونے میں، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بھی سنائی دی۔ یہ ایک فلسفیانہ جدوجہد تھی، جہاں زندگی کا حقیقی مقصد اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا اور اپنی شناخت کے لیے لڑنا تھا۔
چنانچہ، گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک عزم جنم لے رہا تھا، کہ وہ اپنے وجود کی بنیادوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ثقافت اور تاریخی شناخت ہی ان کی زندگی کی حقیقی روح تھی۔ اور اسی روح کے لیے وہ ہر ممکن قربانی دینے کو تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اپنی جڑوں کو کھو دینا، اپنے آپ کو کھو دینا ہے
آوازیں گونجتی رہیں۔
3: جبری گمشدگیوں کی کہانی
ایک دن، گاؤں کے سکوت میں ایک نئی خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ، جو نوآبادکار کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات رکھتے تھے، اچانک غائب ہونے لگے۔ یہ گمشدگیاں صرف افراد کی عدم موجودگی کا سوال نہیں تھیں، بلکہ ایک پوری ثقافت کی دھڑکن کا تھم جانا تھا۔ جبری گمشدگی ایک ایسا عمل تھا جو جسموں کو قید کرنے کے ساتھ ساتھ روحوں کی آزادی بھی سلب کر لیتا ہے۔
گاؤں کی گلیوں میں پھرتے لوگوں کی آنکھوں میں ایک سوال تھا: “کہاں گئے وہ لوگ؟” ان کی گمشدگی ایک تیز چوٹ کی مانند تھی، جو ہر دل میں ایک نیا خوف بھر رہی تھی۔ جو لوگ حق کی آواز بلند کرتے تھے، وہ اب زمین کی آغوش میں چلے گئے، جیسے مٹی نے انہیں اپنے راز چھپانے کے لیے گلے لگا لیا ہو۔
نوآبادکاروں نے بڑی دلیری سے شاطرانہ طور پر یہ بات عام کردی کہ جو نوجوان جبری گمشدہ کیے گئے ہیں، ان کی گمشدگی ایک غیر معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ان کی اپنی چالاکیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان ایک عیاری کی مثال تھی، جس نے مقامی لوگوں کی آنکھوں میں مزید خوف اور بے بسی پیدا کر دی۔
جبری گمشدگیاں صرف فرد کی نہیں ہوتیں؛ ان کے اثرات پورے خاندان اور برادری پر گہرے نفسیاتی داغ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی فرد غائب ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے چھوڑا ہوا خاندان ایک اجتماعی عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ ہر گمشدہ فرد کی عدم موجودگی اس کے خاندان کے ہر رکن پر ایک سایہ بن کر چھا جاتی ہے، جس سے ان کی زندگی میں ایک مسلسل بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ مشہور کالم نگار ہارون رشید نے ایک مضمون میں لکھا ہے، “جب کوئی فرد جبری طور پر غائب ہوتا ہے، تو یہ صرف اس کی جسمانی موجودگی کا ختم ہونا نہیں، بلکہ ایک خواب، ایک امید، اور ایک تاریخ کا مٹ جانا ہوتا ہے، جس کا اثر اس کے پیچھے رہ جانے والوں پر ہمیشہ رہتا ہے۔”
مقامی لوگوں نے انسانی طور پہ زندگی اور موت انہی دو حالتوں کا سامنا کیا تھا، مگر جبری گمشدگیاں ان دونوں کے بیچ ایک نئی حالت کی تخلیق کر رہی تھیں۔ یہ حالت ایک عجیب و غریب خوفناک صورت حال تھی، جہاں افراد کا جسم تو موجود نہیں رہتا، لیکن ان کی روحیں ایک دائمی عذاب میں گرفتار کیے دیتی۔ یہ گمشدگیاں نہ صرف موت کی طرح خوفناک تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ دردناک، کیونکہ یہ امید کے سائے کو بھی چرانے کی کوشش کرتی تھیں جہاں وقت کا مرہم بے سود تھا۔دہاہیوں ایک ہی حالت انسانی ذہن پہ طاری رہتی۔
گاؤں کی خواتین، جو اپنی روایات کی محافظ تھیں، اب نالے کی طرح بہنے والے آنسوؤں سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھیں۔ لیکن وہ محصور تھی کیونکہ آبادکار نے نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی طور پہ بھی ان پہ قدغن لگاے تھے۔اگر اپنی تاریخی قومی کردار کے طور پہ کوئی خاتون اپنا درد بیان کرنے نکلتی تو اسکے کردار کے ساتھ ساتھ اسکے خاندان کو بھی القابات سے نوازہ جاتا اور یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہورہا تھا تاکہ اجتماعات کو روکا جاسکے۔
ہر گمشدہ فرد کے پیچھے ایک کہانی چھپی تھی، ایک خواب جو حقیقت بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ ان کی گمشدگیاں ان کے خاندانوں میں گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑ گئی تھیں، جیسے دھوپ میں سیاہ بادل چھا گئے ہوں۔
خاموشی کا دور دورہ تھا۔
یہ خاموشی ایک سوال کو جنم دیتی تھی: “کیا ہم اپنی آوازیں کھو دیں گے؟” جیسے ہی گاؤں کے لوگ اس درد کو محسوس کرتے، وہ جانتے تھے کہ یہ گمشدگیاں صرف فرد کی نہیں، بلکہ ایک قوم کی نسل کشی کا آغاز ہیں۔
بزرگوں کی آنکھوں میں ایک دانائی کا گہرا سمندر تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ خاموشی ایک خطرے کی علامت ہے۔ فرانز فینن کی “افتادگان خاک” میں کہا گیا ہے، “جب ایک قوم اپنی شناخت کو کھو دیتی ہے تو اس کی روح بھی مر جاتی ہے۔” اسی طرح میکسم گورکی اپنی کتاب “ماں” میں لکھتے ہیں، “آزادی کی جنگ لڑنے والے کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ اپنی قوم کی روح میں زندہ رہتے ہیں۔” یہ الفاظ لوگوں کو حوصلہ دیتے تھے کہ اگرچہ گمشدگیاں ہولناک ہیں، لیکن ان کے دلوں میں گمشدہ افراد کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔
ان کی آنکھوں میں جو درد تھا، وہ ایک مشترکہ گمشدگی کی داستان سناتا تھا۔ جیسے ہی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، وہ جانتے تھے کہ ان کی شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس گمشدگی کے خلاف ایک مزاحمت کی بنیاد رکھنی ہے۔ ان کی خاموشی میں ایک عزم کی جھلک تھی کہ وہ اپنی ثقافت اور اپنی کہانیوں کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے۔
یہ ایک فلسفیانہ جنگ تھی، جہاں گمشدگیوں نے نہ صرف جسموں کو قید کیا بلکہ خوابوں اور امیدوں کی بھی نسل کشی کی۔ لوگ جان گئے کہ ہر گمشدہ فرد کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور راستہ بند ہو گیا، مگر اسی بند راستے کے پیچھے امید کا ایک نیا دروازہ کھلنے کا امکان موجود ہے۔
لہذا، گاؤں کے لوگ ایک نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ وہ اپنی گمشدہ آوازوں کو زندہ رکھنے کے لیے لڑیں گے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ایک بھی آواز باقی رہے گی، وہ اپنی شناخت کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اور ان گمشدہ لوگوں کی یادوں کو کبھی بھی فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عزم نہ صرف ان کی ثقافت کی حفاظت کا عہد تھا بلکہ ایک نئی شناخت کی تلاش کا سفر بھی تھا، جہاں وہ اپنی گمشدگیوں کے درد کو امید کی روشنی میں بدلنے کے لیے تیار تھے۔
4: اجتماعی سزاؤں کی کہانی
نوآبادی کے آتشیں ہاتھوں نے جب زمین کو جکڑنا شروع کیا، تو اس ظلم نے ایک نیا منظر نامہ تخلیق کیا۔ آوازیں اُٹھنے لگی جسکے جواب میں اجتماعی سزائیں شروع ہوئیں، جنہوں نے مقامی لوگوں کی روحوں پر گہرے زخم چھوڑے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو خوف کی بنیاد پر استوار ہوا، جہاں ہر فرد کو اپنے وجود کی بقاء کے لیے لڑنا پڑتا تھا۔
جب نوآبادکار فوجی گاؤں میں داخل ہوتے، تو وہ ایک عزم کے ساتھ چہرے چڑھائے آتے، جیسے وہ کسی بڑے معرکے میں اتر رہے ہوں۔ وہ لوگوں کو بے رحمی سے باہر نکالتے، ان کی آنکھوں میں خوف کی جھلک دیکھ کر بھی بے پرواہ رہتے۔ یہ عمل ایک خوفناک کھیل کی مانند تھا، جہاں انسانی جانیں محض احکامات کی تعمیل میں مٹ رہی تھیں۔
اجتماعی سزائیں محض جسموں کا قتل نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک ثقافتی نسل کشی کا آغاز بھی تھیں۔ مقامی لوگوں کی زندگیاں اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں رہیں، بلکہ ہر ایک کی داستان میں خوف کا عنصر موجود تھا۔ ان کی ثقافت کی جڑیں آہستہ آہستہ کھوکھلی ہونے لگیں، جیسے درخت کی جڑیں خشک ہو جائیں۔ کیا یہ صرف ایک جسمانی قید تھی، یا یہ روح کی بھی قید تھی؟ جب لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیتے، تو ان کی آنکھوں میں ایک سوال جھلکنے لگتا: “ہم کہاں جا رہے ہیں؟” یہ سوال ایک گہرے درد کے ساتھ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا۔
گاؤں کی ہر گلی، ہر چوراہا، اب ایک خاموش گواہ بن چکا تھا، جہاں ہر دل میں ایک درد کی داستان سمائی ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فلسفیانہ سوچ نے جنم لیا: کیا طاقت کا یہ استعمال حقیقی طور پر طاقت ہے، یا یہ صرف ایک عارضی جبر ہے؟ نوآبادکاروں نے سوچا کہ وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے ان کی آوازیں دبا دیں گے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہر ایک سزائے اجتماعی نے مزاحمت کی ایک نئی داستان کو بھی جنم دیا۔
جارج اورویل اپنی کتاب “1984” میں لکھتے ہیں، “جنگ امن ہے، آزادی غلامی ہے، جهل طاقت ہے۔” یہ الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ نوآبادکاروں کا ظلم صرف جسمانی قید تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کی ذہنوں میں بھی خوف کا ایک قلعہ تعمیر کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، تو انہوں نے ایک نئی امید کی کرن پائی۔ وہ جانتے تھے کہ اس ظلم کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہ محض گمشدگیوں اور خوف کی دلدل میں نہیں ڈوب سکتے تھے۔ ان کی ثقافت، ان کی کہانیاں، اور ان کی شناخت ان کے دلوں میں زندہ تھیں۔
وہ سمجھ گئے کہ اس درد کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے: اتحاد اور مزاحمت۔ چنانچہ، اجتماعی سزاؤں کے سائے میں، مقامی لوگوں نے اپنی آوازیں اٹھانے کا عزم کیا۔ ہر آنکھ میں ایک عزم کی چمک اور ہر دل میں ایک نیا عزم بیدار ہوا۔ وہ جان گئے کہ یہ صرف جسموں کی جنگ نہیں، بلکہ ان کی ثقافت کی بقاء کی جنگ ہے۔ اور اسی جنگ میں، وہ اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر ظلم کا ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب انہیں خود ہی دینا تھا۔
یہ ایک عزم تھا، جو ان کی شناخت کی جنگ کی شروعات کی بنیاد بن گیا۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی کا راستہ کٹھن ہے، مگر انہیں یہ بھی علم تھا کہ ایک نئی صبح کی کرن ہر ظلم کے بعد ابھرتی ہے۔ یہی ان کی حقیقت بن گئی، کہ ظلم کا ہر سایہ ایک نئی روشنی کے سفر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
نوآبادکار کی دھمک کے سائے میں، جب کسی نوجوان کی مسخ شدہ لاش ویرانے میں پڑی ملتی، تو اس خبر کی مانند ایک طوفان گاؤں میں پھیل جاتی۔ ہر گمشدگی کے شکار خاندان کا دل دھڑکنے لگتا، جیسے ان کی روحوں میں ایک نئی درد کی لہر دوڑ گئی ہو۔ عورتیں، مرد، اور بچے، سب ایک ساتھ اُس جگہ کی طرف دوڑتے، جہاں موت نے اپنی خونی قبا اوڑھ رکھی تھی۔
جب وہ پہنچتے، تو منظر دل دہلا دینے والا ہوتا۔ مسخ شدہ چہرہ چھلنی جسم، جس کی آنکھیں نکالی جاچکی تھی،(گاوں میں مصدقہ طور پہ یہ کہانیاں عام تھی کہ آبادکار گمشدہ افراد کے آرگنز فروخت کرہی ہے تاکہ انکی ہڈیوں سے بھی فاہدے وصول کیے جاسکیں) وہ بےجان جسم بے بسی کی تصویر تھا۔ خاندان کے افراد، زخموں سے چور، اپنی امیدوں کی آخری کرن کی تلاش میں، آہستہ آہستہ اُس لاش کے گرد جمع ہو جاتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا: “کیا یہ ہمارا لخت جگر ہے؟”
وہ ہر سمت سے اُس جسم کو ٹٹولتے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ برتھ مارکس اور نشانیوں پہ اکتفاء کیا جاتا، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی صورت اُن کے پیارے ہوسکتے ہیں۔ٹارچر کا ہر نشان، ہر خراش، ان کے دل میں ایک نیا درد بھر دیتا۔ کیا یہ ان کا بیٹا ہے؟ کیا یہ اُن کا بھائی ہے؟ ہر گزرتا لمحہ ان کے دلوں کو کچلتا، اور درد کی ایک نئی داستان سناتا۔
اس خاموش ویرانے میں، جہاں ہوا کی سرگوشی بھی خوفناک لگتی تھی، ایک گہرا سناٹا چھا جاتا۔ وہی سکوت، گمشدگیوں کی ایک نئی داستان کو جنم دیتا۔ یہ صرف لاش نہیں تھی، بلکہ ایک پوری ثقافت کی داستان تھی، جو اس ظالم وقت کی قید میں تھی۔
جب وہ واپس پلٹتے، تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر ہوتا، دلوں میں امیدوں کا بکھراؤ۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک لاش کا درد نہیں، بلکہ ایک قوم کی روح کا کرب ہے۔ ہر گمشدہ جوان، ہر مسخ شدہ جسم، ان کی تاریخ کا ایک حصہ تھا، جسے نوآبادکار نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر ان کی کہانیاں زندہ رہیں گی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر درد کی داستان اپنے اندر کہیں آغاز چھپائے ہوئے ہے۔
اسی لمحے میں، ان کی مزاحمت کی روح ایک نئی زندگی پا لیتی۔ وہ جان گئے کہ ان کی شناخت کی جنگ جاری رہے گی، اور ہر لاش کی کہانی ان کی جدوجہد کی طاقت بن جائے گی۔ یہ درد، یہ مایوسی، اور یہ مسخ شدہ لاشیں، سب ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھ رہی تھیں۔
5: ٹارچر کی کہانی
نوآبادکار ان تمام رویوں کا مشاہدہ کررہا تھا تو ایک اور نفسیاتی وار کے ساتھ میدان میں اترا جب ایک دن گاوں کے قبرستان کے پاس
اجتماعی قبروں کا ذکر ہوا تو دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ زمین میں کھودے گئے گڑھے، جہاں دو سو کے قریب بے گناہوں کی لاشیں ، خاموشی میں ایک دردناک داستان سناتے تھے۔ چُونا لگی یہ لاشیں سڑنے کیلئے ایک گڑھے میں پھینکی گہی تھی تاکہ انکی کہانیوں کو بھی چہروں کی طرح مسخ کیا جاسکے اس بات کی گواہی دیتی تھیں کہ مقامی لوگوں کی زندگیوں کی کوئی قدر نہیں رہی۔
اسکے ساتھ ہی ٹارچر کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ
بیابانوں میں پڑی دو دو تین تین لاشیں۔
کچھ پھیڑوں سے ٹنگی ماوں کے لخت جگر کی لاشیں جنکے سینوں پہ سگریٹ سے جلاے جانے کے نشانات، جسم پر چہتروں کے گہرے نیلے زخم، ان کی بے جان کھلی خشک آنکھوں میں ایک عزم یکساں تھا، جو
بتاتا تھا کہ وہ ہر درد کے باوجود زندہ رہنے کی کوشش کررہے تھے۔
گاؤں کے لوگوں نے جب ان کہانیوں کو دیکھا سنا، تو ان کے دلوں
میں ایک نئی آگ بھڑک اُٹھی۔ یہ محض ذاتی درد نہیں تھا،
بلکہ ایک قوم کی روح کو چوٹ پہنچانے کی کہانی تھی۔ انہی کچھ مہینے بعد، گاؤں کی فضاؤں میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ اور پھر چند خوشخبریاں جب کچھ گمشدہ لوگ واپس لوٹے،نوآبادکار کے کاسہ لیسوں نے انھیں اپنی سفارتی کامیابیوں سے تشبیہ تو دی لیکن رہا کیے گئے افراد کی حالت ایسی تھی جیسے زندگی کے سچے خزانے کو کھو کر آئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک گہری لہر، اور دلوں میں درد کا سمندر تھا۔ وہ اب بھی نوآبادکار کے ہاتھوں کی مار کے اثرات کو محسوس کر رہے تھے، جیسے ہر زخم کی داستان ان کی روحوں میں بکھری ہوئی ہو۔
جیسے ہی وہ اپنے خاندانوں کے سامنے آئے، ایک لمحہ کے لیے دنیا رک گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
یہ ان کی کہانیوں میں محض ذاتی تجربات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک پوری ثقافت کے درد کا اظہار تھے۔ ان کی گمشدگیوں نے صرف جسموں کو ہی نہیں بلکہ امیدوں اور خوابوں کو بھی قید کر لیا تھا۔ جب وہ اپنے درد کی داستانیں سناتے، تو ہر سننے والا محسوس کرتا کہ یہ محض ان کے زخم نہیں، بلکہ ایک قوم کے زخم ہیں۔
ان کی کہانیاں، جو خوف کی گہرائیوں میں دفن تھیں، اب ایک نئی حقیقت کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ ہر لفظ ایک گہرے سوال کی مانند تھا:
“کیا ہم اپنی ثقافت اور شناخت کو کبھی بھی بحال کر سکیں گے؟”
یہ سوال نہ صرف ان کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے تھا جو اس بربریت کے دور سے گزر رہا تھا۔
فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک عمیق حقیقت کا عکاس تھا: جب ایک قوم کی روح کو توڑا جاتا ہے، تو اس کے نتائج صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی بھی ہوتے ہیں۔ ان گمشدہ لوگوں کی کہانیاں ان کی ثقافتی طاقت کی علامت تھیں، اور یہ بتاتی تھیں کہ انسان کی روح کو کچلنا ممکن نہیں۔
اسی لمحے میں، مقامی لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی مزاحمت کی داستان میں ایک نئی شروعات ہو رہی ہے۔ ان کی درد کی کہانیاں اب ایک نئی امید کا پیام لاہی ہیں۔ وہ جان گئے کہ جتنے بھی زخم ان پر لگے، وہ ان کی شناخت کی جڑیں نہیں توڑ سکتے۔
وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کر چکے تھے۔
اپنے زخموں کے باوجود، وہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں گے، اور ان کی کہانیاں کبھی نہیں مٹیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ درد کی یہ کہانیاں ان کی جدوجہد کی طاقت بنیں گی، اور ان کے لیے ایک نئی روشنی کا راستہ ہموار کریں گی۔ ان کے اندر ایک امید کی شمع روشن تھی، جو ہر ظالم کے سامنے کھڑی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر درد کی داستان میں ایک نیا آغاز چھپا ہوتا ہے۔
6: مزاحمت کی کہانی۔
اب خاموشی حقیقی موت تھی۔
ہر ظلم کے خلاف ایک مزاحمت جنم لیتی ہے،
ہم چھپ نہیں رہیں گے اب گاوں کی ایک ننی پری اور چند عورتیں بازار کہ چوک پہ بیٹھی اپنے گمشدہ بھائی کیلئے نعرے لگا رہی تھی
“ہم بھائی بچانے نکلے ہیں_ آو ہمارے ساتھ چلو”۔
گاوں میں اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے مقامی لوگوں نے اپنی کہانیوں کو بیدار کیا۔ جب نوآبادکار کی بربریت نے گاؤں کی فضاؤں میں خوف کی چادر تان دی، تو مقامی لوگوں نے درد سے تنظیم لی۔
یہ تنظیم محض ایک جماعت نہیں تھی، بلکہ ایک امید کی کرن تھی، ایک ایسی تحریک جس کا مقصد ان کی شناخت ثقافت اور لوگوں کا تحفظ کرنا تھا۔
ان کے دلوں میں ایک گہرے درد کے ساتھ یہ عزم موجود تھا کہ اگر وہ اپنی کہانیوں کو زندہ رکھیں گے تو اپنی شناخت کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ان کی کوششیں گمشدہ لوگوں کی تلاش میں صرف ایک عمل نہیں تھیں، بلکہ ایک جذباتی، فلسفیانہ جستجو بھی تھیں۔ جیسا کہ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب “Orientalism” میں کہا، “تاریخ کی تحریر ہمیشہ طاقت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔” یہ مقامی لوگ اپنی کہانیوں کے ذریعے اس طاقت کو چیلنج کرنے کا عزم رکھتے تھے۔
جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے، تو ان کی آنکھوں میں ایک درد کا سمندر ہوتا۔ ایک بوڑھی ماں، جس نے اپنےنوجوان بیٹے زاکر کو 15 سال پہلے کہانی بنتے دیکھا تھا جو تاحال جبری گمشدہ تھا، بولی
“ہماری کہانیاں ہماری روحوں کا آئینہ ہیں ہماری کہانیاں ہمارے بچے ہیں۔ جب ہم اپنی کہانیاں بھول جائیں گے، تو کیا ہم واقعی زندہ رہیں گے؟”
یہ سوال ہر دل میں گونجتا تھا، جیسے ایک دھماکے کے ساتھ کوئی خالی پن پیدا کر دیتا۔
ان کی محفلیں اب صرف گفتگو کا مقام نہیں تھیں، بلکہ ایک گہرے درد کی عکاسی کر رہی تھیں۔ جب وہ جبری گمشدہ اور شہیدوں کی یادیں تازہ کرتے، تو ہر آنکھ میں آنسو بھر آتا، اور ہر دل میں ایک طوفان اٹھتا۔ یہ درد جسکا مچل فوکو اپنی کتاب “Discipline and Punish” میں حوالہ دیتے ہیں کہ کس طرح طاقت کے استعمال کے ذریعے لوگوں کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کس طرح نوآبادکار سماجی طاقتیں تشکیل دیتی ہے لوگوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے اور مختلف طریقے اختیار کرتی ہیں، جس سے ان کی زندگیوں میں درد اور خاموشی پیدا ہوتی ہے۔ اس اقتباس میں دراصل اس بات کی عکاسی کی گئی ہے کہ یہ درد نہ صرف فردی تجربات کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ایک بڑے سماجی مسئلے کا بھی اشارہ ہے جہاں لوگوں کو ان کی آوازوں سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن کہانیاں مرتی نہیں۔
وہ جانتے تھے کہ یہ مزاحمت محض ایک جسمانی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی ثقافت اور شناخت کی بقاء کی جنگ تھی۔ ہر میٹنگ میں، جب وہ اپنے تجربات کا تبادلہ کرتے، تو ان کی کہانیاں ایک نئی حقیقت کو جنم دیتیں۔ ایک نوجوان لڑکی، جس نے اپنی ماں کو لاپتہ بھائی کے درد میں تڑپتے ہوئے کھو دیا تھا، خاموشی سے بولی، “میری ماں اور بھائی کی کہانی میری زندگی کا احصہ ہیں۔
جب تک میں زندہ ہوں، میں اسے بُھولنے نہیں دوں گی۔
فلسفیانہ طور پر، یہ مزاحمت ایک گہرے سچ کی نمائندگی کرتی تھی:
جب ایک قوم کی کہانیاں چوری ہو جاتی ہیں، تو اس کی روح کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ مگر جب وہ اپنے دل کی آواز سُناتے ہیں، تو وہ ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں درد اور خوف سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ان میں امید کا ایک گہرا رنگ بھی شامل تھا اور اجتماعی کی نوید وہ درد سے جُڑے تھے جسنے انکی مضبوط تنظیم کاری کی۔
ان کی یہ تنظیم، جو خوف کے سائے میں ابھری تھی، اب ایک نئی روشنی کا سفر طے کر رہی تھی۔ ہر لفظ جو وہ بولتے، ہر قدم جو وہ اٹھاتے، ایک عزم کی گواہی تھی کہ وہ اپنی ثقافت کو مٹنے نہیں دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر ظلم کے خلاف مزاحمت ایک نئی داستان تخلیق کرتی ہے، اور یہ داستان ان کی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کرے گی۔
یہ جدوجہد، جیسا کہ حنا آرنت نے اپنی کتاب “On Revolution” میں لکھا ہے، انسانی وقار اور آزادی کی جستجو میں ایک لازمی عنصر ہے۔ مقامی لوگ اپنی کہانیوں کو محفوظ نہیں رکھیں گے بلکہ انہیں ایک نئی زندگی دیں گے۔ ان کی مزاحمت ایک نیا فلسفہ بن جائے گی، جو یہ بتائے گا کہ حق اور انصاف کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی
چنانچہ، جب تک ایک بھی آواز باقی رہے گی، وہ اپنی شناخت کے لیے لڑتے رہیں گے، کیونکہ ان کی کہانیاں، ان کا درد، اور ان کی امید ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھیں گی۔ یہ مزاحمت نہ صرف ان کے لیے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک چراغ کی مانند ہوگی، جو تاریکی میں
راہنمائی کرے گی وہ اپنی شناخت کے لیے لڑتے رہیں گے، کیونکہ ان کی کہانیاں، ان کا درد، اور ان کی امید ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھیں گی۔ یہ مزاحمت نہ صرف ان کے لیے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک چراغ کی مانند ہوگی، جو تاریکی میں
راہنمائی کرے گی۔
7: فلسفہ کردار اور امید کی کہانی
مزاحمت کی اس داستان میں ایک گہری فلسفیانہ بنیاد موجود ہے۔ جیسے ہی مقامی لوگ اپنے زخموں کی داستانیں سناتے، ان کی آوازوں میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے دلوں کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی صدا تھی، جو انسانیت کی حقیقی آزادی کی جستجو کی عکاسی کرتی تھی۔ جیسا کہ ہیگل نے کہا، “تاریخ کے جبر میں آزادی کی جستجو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔”
یہ مقامی لوگوں کی جدوجہد دراصل ایک عمیق حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، جہاں فرد کی آزادی تاریخی، ثقافتی شناخت، اور اجتماعی مزاحمت کے عناصر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ظلم کا سامنا کرنا صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفیانہ جنگ بھی ہے۔ ان کی کہانیاں ایک نئے شعور کا آغاز تھیں، جو ان کے وجود کو نئی روشنی عطا کرتی تھیں۔
ایک نوجوان لڑکے نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، “جب میرے بھائی کو غائب کیا گیا، تو میں نے سمجھا کہ میں بھی غائب ہوں۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی کہانی کو زندہ رکھ کر اپنے بھائی کو دوبارہ پا سکتا ہوں۔” یہ باتیں ہر ایک کے دل میں گونجنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، جو ہر ظلم کے سائے میں ایک نئی روشنی کی صورت میں ابھرتی تھی۔
اس مزاحمت کی جڑیں ثقافتی ورثے میں گہری تھیں، جیسا کہ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب “Culture and Imperialism” میں واضح کیا ہے کہ ثقافت ہمیشہ طاقت کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار بن سکتی ہے۔ مقامی لوگ اپنی شناخت کو بحال کرنے کے لیے ایک نئی راہ تلاش کر رہے تھے، جو ان کی ثقافتی روایات، زبان، اور یادوں کے گرد گھومتی تھی۔
چند لمحوں کے لیے، خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک بزرگ شخص نے کہا، “ہماری کہانیاں صرف ہماری نہیں، بلکہ ہماری نسلوں کی ہیں۔ جب ہم اپنی کہانیاں سناتے ہیں، تو ہم اپنی روحوں کو آزاد کرتے ہیں۔” یہ الفاظ ایک عزم کی علامت بن گئے۔ ہر ایک نے محسوس کیا کہ ان کی کہانیاں صرف ان کے ذاتی تجربات نہیں، بلکہ ایک قومی یادداشت کا حصہ ہیں۔
ان کی آوازوں میں ایک نئی قوت تھی، جو ہر خوف کے سایے کو چھانٹتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ امید ایک ایسی طاقت ہے جو ہر ظلم کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی کہانیاں سناتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے گئے۔ ہر درد، ہر قربانی، اور ہر آواز، ایک مشترکہ شناخت کی تشکیل کرتی تھی۔
چنانچہ، وہ جان گئے کہ ان کی مزاحمت نہ صرف ان کے لیے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوگی۔ ان کی کہانیاں ایک نئے فلسفے کی بنیاد رکھیں گی، جو یہ بتائے گی کہ انسان کی روح کی آزادی کا راستہ اس کی ثقافتی شناخت اور انسانی وقار میں مضمر ہے۔
جیسے کہ Hannah Arendt گویا ہوے کہ”آزادی کا مطلب صرف سیاسی طاقت نہیں، بلکہ خود کو منوانا ہے۔” یہ لوگ اب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی داستانیں ایک نئی حقیقت کی تشکیل کر رہی ہیں۔
ان کی مزاحمت کا یہ سفر، ایک نئے آغاز کا نشان ہے، جہاں ہر کہانی میں امید کی کرن ہے، جو تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ جدوجہد ایک عزم کی علامت ہے کہ جب تک ایک بھی آواز باقی رہے گی، وہ اپنی شناخت اور آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔
8: بے خوف قوم کے عزم کی کہانی
وقت کے گزرنے کے ساتھ، مقامی لوگوں کی مزاحمت کی داستانیں دور دور تک پھیل گئیں۔ خوف کی چادر چیر کر، وہ اب ایک بے خوف قوم کے طور پر ابھرے۔ جب نوآبادکار کے نمائندے گاؤں میں آئے، تو انہوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو ان کے دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ لوگ اپنی لیڈر، ایک نوجوان لڑکی، کے ساتھ صف باندھے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم اور دلوں میں ایک نئی قوت کی جھلک تھی۔ ان کی کہانیاں اب ان کے وجود کا حصہ بن چکی تھیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے کو تیار تھے۔
یہ لڑکی، جس کا بچپن اپنے باپ کی درد بھری کہانیوں میں گزرا، اب ایک قومی رہنما بن چکی تھی۔ اس کے باپ کو دو بار جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ پہلی بار جب وہ گاؤں کی آواز بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو نوآبادکار نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی گمشدگی کے دوران سخت تشدد برداشت کیا، لیکن وہ اپنی کہانی سنانے کا عزم نہ چھوڑ سکا۔ اسکی چھوٹی بچی رو رو کر سڑکوں پہ اپنی کہانی سنا رہی تھی جب وہ واپس آیا، تو اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، لیکن اس کی بچی کے کردار نے اسکے روح میں ہمت کا چراغ روشن کردیا تھا کہ یہ ہمت نسل در نسل منتقل ہورہی ہے۔
لیکن پھر دوسری بار، جب وہ دوبارہ آواز اٹھا رہا تھا، اسے پھر لاپتہ کیا گیا۔گاوں والوں کے ساتھ ساتھ اسکی بچی کو بھی یقین ہوچلا تھا کہ وہ اپنے والد کو ان درندوں کے چنگل سے نکال لے گی لیکن اس بار، جب اس کی مسخ شدہ، تشدد زدہ لاش اسکی بچی کو واپس کی گئی، تو اسکی دنیا تہہ و بالا ہو گئی۔
جس نے اس بچی کا بچپن چھین لیا یہ ایک دردناک منظر تھا، جس نے اس لڑکی کے دل میں ایک نئی آگ بھڑکائی۔ اس نے اپنے باپ کی کہانی کو زندہ رکھنے کا عزم کیا، اور لوگوں کے سامنے اپنی آواز بلند کی۔
اس نے بلند آواز میں کہا، “میرے باپ کو خاموش کرنے کی تمہاری کوششیں ناکام ہو گئیں! ہم اس درد کو اپنے دلوں میں لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اپنی کہانیوں کو زندہ رکھیں گے، اور اب ہم ایک قوم کے طور پر کھڑے ہیں!” اس کی آواز میں وہ قوت تھی جو ہر ایک کے دل کو جیت لیتی تھی۔
یہ منظر ایک نئی صبح کا نشان تھا، جہاں ہر ایک کو معلوم تھا کہ آزادی کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اپنی سرزمین اور ثقافت کا دفاع کرنا ہے تو انہیں ایک ساتھ ہونا ہوگا۔ ان کے دلوں میں ایک عزم تھا کہ اب وہ نوآبادکار کے ظلم کا سامنا کریں گے، اور اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔
یہ بے خوف قوم، جو اپنے درد اور قربانیوں سے سبق سیکھ چکی تھی، اب ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے تیار تھی۔ جیسا کہ فلسفی ہیگل نے کہا، “آزادی ایک عمل ہے، ایک جدوجہد ہے جو ہر نسل کے دل میں زندہ رہتی ہے۔” وہ لوگ اب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت رکھتے تھے، اور ان کی کہانیاں ایک نئی شمع کی مانند روشن تھیں۔
اس لمحے، نوآبادکار کے نمائندے سمجھ گئے کہ وہ صرف طاقت اور ہتھیاروں کے بل پر نہیں جیت سکتے۔ ایک قوم کی طاقت اس کی شناخت، ثقافت، کہانیوں، اور جدوجہد میں ہوتی ہے۔ اور اس بار، ایک بے خوف قوم کھڑی تھی، جو اپنی سرزمین کے لیے لڑنے کو تیار تھی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینا پڑیں۔
یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک نئی باب کا آغاز ہے، جہاں ہر دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن ہو رہی ہے، اور ہر آواز ایک نئی کہانی تاریخ کے صفحے پر لکھنے کو تیار ہے۔ اس لمحے نے ان کی شناخت کو مزید مضبوط کیا ہے، اور یہ عزم انہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ ایک قوم کی بقاء شناخت اور اس کی ثقافتی ورثے کی حفاظت کا سفر ہے۔
کہانیاں جاری ہیں۔۔۔
دی بلوچستان پوسٹ: اس تحریر میں پیش کیئے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کے پالیسیوں کا اظہار ہیں۔