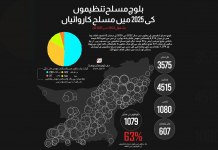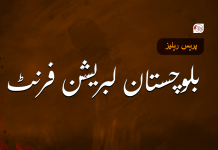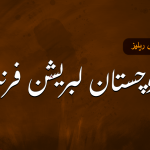استعماری لغت کا انہدام
تحریر: برزکوہی
دی بلوچستان پوسٹ
پنجابی نوآبادیاتی نظام اپنی پیدائش سے ہی اُس غلیظ تاریخ کا تسلسل ہے جو مختلف چہروں اور زبانوں میں محکوموں کو مٹانے کا فن جانتی ہے۔ لیکن بلوچ کے ماتھے پر لکھی ہوئی یہ مزاحمت کی پیشانی کسی بھی نظریاتی یا عسکری شکست کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس لیے پنجابی ریاست نے اپنی پوری مشینری، ریاستی طاقت، دینی تخریبات، میڈیا کی دُھند، اور یونیورسٹیوں کے گٹھ جوڑ سے پیدا ہونے والی جعلی دانش کو بلوچ اجتماعی شعور کے خلاف صف بند کر رکھا ہے۔ لیکن مسئلہ فقط طاقت کا نہیں، مسئلہ فہم کا ہے، اور بلوچ قوم وہ قوم ہے جو فہم کی کوکھ سے جنم لینے والی جنگ لڑ رہی ہے، جو خون سے نہیں، مگر خون سمیت، جو محض حرف سے نہیں مگر حرف سمیت، اور محض روایت سے نہیں مگر روایت سمیت چلتی ہے۔
ہماری نسل کشی فقط لاشوں میں نہیں، لغت میں بھی ہے، تعلیمی نصاب میں بھی ہے، بچوں کی نظموں، میڈیا کی خبروں میں بھی ہے۔ بلوچ کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ یہ ہے کہ اُس کی کمزوری کو ریاست نے مسلسل دہرا کر حقیقت بنانے کی کوشش کی ہے پھر اس جعلی حقیقت پر بلوچ کو یقین دلانے کی پوری کوشش کررہا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں مزاحمت صرف بندوق سے نہیں بلکہ فکر سے شروع ہوتی ہے، وہ فکر جو اپنا تعارف خود لکھتی ہے، جو اپنی تاریخ خود بیان کرتی ہے، جو پنجابی مؤرخین کے لکھے ہوئے جھوٹ کو قبول نہیں کرتی، اور جو اپنی زبان سے اپنے خون کا مقدمہ لڑتی ہے۔
استعمار صرف بندوق سے نہیں بولتا، وہ سب سے پہلے زبان بدلتا ہے اور جب لغت پر قبضہ ہو جائے تو زمین پر قبضہ محض ایک رسمی کارروائی رہ جاتی ہے۔ لغت، وہ خفیہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے استعمار معنی کا تعین کرتا ہے، مزاحمت کو جرم، غلامی کو وفاداری، اور استحصال کو ترقی کا نام دیتا ہے۔ جب لغت قابض کی ہو جائے، تو محکوم اپنی زبان میں بھی دشمن کے مفہوم میں سانس لیتا ہے۔ اور یہی وہ پہلا محاذ ہے جہاں قابض قوت حملہ آور ہوتا ہے، الفاظ و بیانیئے کا حملہ۔
پنجابی نوآبادیاتی ریاست پاکستان نے بھی سب سے پہلے لغت کو مسخر کیا۔ اُس نے قوم کے مفہوم کو فقط اس اکائی تک محدود کردیا جو اُس کے قومی بیانیے سے وفاداری ظاہر کرے۔ اُس نے “ترقی” کو اُن منصوبوں سے جوڑ دیا جن کا خراج بلوچ کی لاش، اُس کی زمین، اور اُس کی خاموش ماں تھی۔ اُس نے “امن” کو ان آپریشنز سے تعبیر کیا جو گاؤں کے گاؤں نیست و نابود کر گئے، اُس نے “وحدت” کو اس زنجیر میں بدلا جس میں ہر بلوچ کو گمشدہ، خاموش یا تابعدار ہونا تھا۔
یہ وہی لغت ہے جس میں بلوچ کو “ناراض”، بلوچ عورت کو “بے حیا دہشتگرد”، بلوچ بندوق کو “دہشتگردی”، اور بلوچ فکر کو “غیرملکی ایجنڈا” کہا جاتا ہے۔ اس لغت میں بلوچ کا سوال فساد ہے، اُس کی شناخت مسئلہ ہے، اور اُس کی آزادی جرم۔
ہمارا بیانیہ اب مزید ان لغات کا اسیر نہیں، ہمارا بیانیہ اب بندوق سے نکلی گولی، عورت کے چیخنے والے سوال، گمشدہ مردہ جسم، اور سیاسی گرفتاری سے کشید ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ریاست کو عورت کی آزادی نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی عورت چاہیے جو ریاستی بیانیے کا پوسٹر بن جائے۔ لیکن بلوچ عورت، جو ماضی میں بھی ایک مزاحمتی وجود تھی، اب صرف ماں، بہن، یا بیٹی نہیں رہی۔ وہ انقلابی ہستی بن چکی ہے، جو نہ صرف مزاحمت کرتی ہے بلکہ بیانیہ بھی تخلیق کرتی ہے۔
لیکن بلوچ قوم اب اس لغت سے انکار کر چکی ہے۔ یہ لغت جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہی لغت ہے جس میں مزاحمت کو جرم اور غلامی کو وفاداری کہا جاتا ہے۔ لیکن بلوچ کے لیے لغت اب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ میدانِ جنگ ہے۔ ہم نے ان الفاظ سے وہ معنی چھین لیے ہیں جو پنجابی ریاست نے ہم پر مسلط کیے تھے۔ “ترقی”، “قومی دھارا”، “ملکی سلامتی” یہ سب مفروضے ہیں، جن کے پیچھے صرف ہماری زمین، ہماری زبان، اور ہمارے خوابوں کی لوٹ مار چھپی ہے۔
ماہ رنگ بلوچ کی گرفتاری محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ نوآبادیاتی خوف کا اظہار ہے۔ جب عورت، جو تاریخی طور پر مظلوم سمجھی جاتی ہے، مزاحمت سے بات کرے، بیانیہ لکھے، یا تنظیم کرے تو وہ نوآبادیات کے تمام ستونوں کو لرزا دیتی ہے۔ کیونکہ نوآبادیاتی نظام، جیسا کہ فینن سمجھاتے ہیں، عورت کی آزادی سے زیادہ اس کی متوقع خاموشی سے جڑا ہوتا ہے۔ بلوچ عورت، ماہ رنگ ہو یا سمی ہو بیبو، صبیحہ ہو یا گل ذادی ہو خاموش نہیں رہتی۔ وہ کالونیل ڈھانچے کی بنیاد پر سوال رکھتی ہے، اور یہی سوال ریاست کے پورے فکری توازن کو برباد کرتا ہے۔
بلوچ عورت اب صرف “ماں” یا “بہن” کی علامت نہیں، بلکہ عملی مزاحمت کی خالق ہے۔ وہ “مقدس” نہیں وہ متشکک ہے۔ اور ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ عورت ہے جو سوال کرتی ہے، جو مزاحمت کرتی ہے، اور جو اس لغت سے انکار کرتی ہے، جس میں عورت کو یا تو ماتم کرنے والی یا خاموش رہنے والی سمجھا جاتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جہاں مزاحمت، جنس کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتی۔ مزاحمت جب قوم بن جائے تو مرد و زن نہیں رہتی، صرف انکار کرنے والے اور اطاعت کرنے والے رہ جاتے ہیں۔ اور ہم انکار کرنے والوں میں ہیں۔ ریاست اس انکار سے بدحواس ہے۔ اس لیے وہ جیل میں قید لڑکی کو بھی “سازشی نیٹ ورک” کا حصہ قرار دیتی ہے۔ وہ بینر و پلے کارڈ اٹھانے والی کو “خودکش” اور قلم چلانے والی کو “غیرملکی ایجنٹ” کہتی ہے۔ لیکن جیل کی کوٹھری میں بھی جب عورت اپنی آنکھوں سے نظریہ لکھتی ہے، تو ریاست کے سب بیانیے مفلوج ہو جاتے ہیں۔
یہاں فوکو کی وہ بات یاد آتی ہے کہ طاقت صرف وہی نہیں جو جسم پر عمل کرتی ہے، طاقت وہ بھی ہے جو سچ کے نام پر جھوٹ مسلط کرتی ہے۔ پنجابی ریاست نے بھی یہی کیا، اپنے ہر زخم کو انصاف، ہر آپریشن کو امن، اور ہر لاش کو “دہشتگرد” کہا۔ لیکن بلوچ قوم اب ان تمام سچائیوں کے پیچھے جھانک چکی ہے اور بلوچ نے ان تمام پرفریب چپچپے الفاظ کو اپنے لغت سے نکال دیا ہے۔
پنجابی ریاست کا سب سے خوفناک پہلو وہ نہیں جو ٹینک میں بیٹھا ہے، بلکہ وہ ہے جو لغت و ڈسکورس میں بیٹھا ہے۔ یہ ریاست صرف فزیکل تسلط سے نہیں چلتی، بلکہ وہ ذہن پر اپنی گرفت کو “قومی وحدت”، “دینی ہم آہنگی”، اور “ترقیاتی مفاد” کے لبادے میں ملفوف کر کے پیش کرتی ہے۔ اگرچہ اس ریاست کی وردی پر خون کے دھبے واضح ہیں، مگر اس کے الفاظ پر جھوٹ کی چمک زیادہ شدید ہے۔ یہ وہی جھوٹ ہے جسے وٹگنسٹائن اپنی فلسفیانہ زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ “معنی، استعمال سے جنم لیتا ہے۔” ریاست نے ان اصطلاحات کا ایسا استعمال رائج کر دیا ہے کہ جن سے غلامی، وفاداری بن جاتی ہے؛ اور مزاحمت، بغاوت۔ بلوچ مزاحمت نے یہی فکری اُلٹ پھیر پہچان لی ہے اور اب یہی ریاستی ڈسکورس اُس کے گلے میں اُلٹا پھندہ بن گیا ہے۔
پوسٹ ماڈرنسٹ مفکرین، جیسے دریدہ، اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ نوآبادیاتی طاقتیں اپنی شناخت، اپنے اقتدار اور اپنے مظالم کو “غیرمرئی” بنانے کے لیے ایسی لغت تراشتی ہیں جو ان کے اپنے مفاد کی سچائی بن جائے۔ پنجابی ریاست بھی بلوچ کے خلاف یہی کرتی ہے۔ وہ “سکیورٹی” کہہ کر لاش گراتی ہے، ترقی” کہہ کر وسائل لوٹتی ہے، ملک دشمنی” کہہ کر سوال کی زبان کاٹتی ہے۔
گرامچی اس عمل کو ثقافتی بالادستی کہتا ہے۔ ایک ایسا نظامِ فکر جس میں ریاست صرف طاقت سے نہیں بلکہ اداروں، نصاب، میڈیا اور مذہب کے ذریعے “رضامند غلامی” کو پیدا کرتی ہے۔ اسکول وہ جگہ بن جاتے ہیں جہاں بلوچ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے آباو اجداد “وحشی” تھے، ان کی ثقافت پسماندہ ہے، اور ان کی زبان “ریجنل” ہے۔ جیسے پنجابی تہذیب کوئی “مرکزِ دانش” ہو، جس کے سامنے سب کچھ سرنگوں ہو۔ یہ تمام فکری غلامی صرف بندوق سے نہیں، بلکہ کالموں، نصابی کتابوں، ڈاکومنٹریز، اور ٹی وی اینکرز کے ذریعے بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ سافٹ پاور ہے جو جسم نہیں کاٹتی، ذہن کاٹتی ہے۔
اسی ذہنی یلغار کا جواب اب بلوچ قوم نے سختی سے دیا ہے۔ ہم نے صرف لاشوں پر ردعمل نہیں دیا، ہم نے ان کے “الفاظ کے جال” کو بھی توڑا ہے۔ ہم نے ترقی کی تعریف بدلی، حب الوطنی کی نوعیت بدلی، اور سب سے بڑھ کر، ہم نے غلامی کو “ناراضگی” کہنا بند کر دیا ہے۔
بلوچ مزاحمت کو سب سے زیادہ تکلیف ان بموں سے نہیں، بلکہ ان تبصروں سے ہوتی ہے جو دبے دبے لہجے میں، نفیس اصطلاحوں میں، اور سماج میں “رواداری” کے نمک میں لپٹے ہوتے ہیں۔ ایک طرف فوجی ٹرک میں لاش جاتی ہے، دوسری طرف “لبرل” اینکر ٹی وی پہ بتاتا ہے کہ بلوچ مسئلہ دراصل پسماندگی کا ہے، اور ریاست اگر تھوڑی سی توجہ دے دے تو “ناراض بھائی” راہِ راست پر آ سکتے ہیں۔
ہم ان دانشوروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مگر صرف طنز کے ساتھ۔ کیونکہ وہ فکری غلامی کو اتنی مہارت سے پیک کرکے بیچتے ہیں کہ فینن بھی قبر میں مسکرا جائے۔ یہی وہ مقام ہے، جہاں طنز، فقط اظہار نہیں، بلکہ ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہم طنز کرتے ہیں اس نظام پر جو ہماری گمشدگی کو “قانونی گرفتاری” کہتا ہے، اور پھر اس پر “عدالتی کمیشن” بٹھا کر انسانیت کا جنازہ سلیقے سے پڑھتا ہے۔ طنز کرتے ہیں اس میڈیا پر جو ماہ رنگ بلوچ کی گرفتاری کو تو نمایاں کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ریاست کے بیانیے کو من و عن نقل کرکے سمجھتا ہے کہ وہ “غیرجانبدار” ہے۔
یہ غیرجانبداری دراصل وہی فکری ملی بھگت ہے جس کا خاکہ گرامچی نے کھینچا تھا یعنی “سیول سوسائٹی کی وہ قوتیں جو اقتدار کے بیانیے کو مقبول بنانے کا کام کرتی ہیں”۔ یہاں صحافت وہ دستانہ ہے جس کے نیچے ریاست کی آہنی گرفت چھپی ہوئی ہے۔
ریاست کو بندوق سے زیادہ خوف اس فکری لغت سے ہے جسے بلوچ قوم نے ریورس انجینیئر کیا ہے۔ ہم نے “معصوم پنجابی مزدور” کی لغت میں وہ استعماری آئینہ دیکھا ہے جس میں ہر قاتل کو معصوم اور ہر مزاحمت کار کو درندہ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن جس زمین پر مزدور صرف وہی کہلائے جو ریاستی ایجنسی کا آلہ ہو، وہاں بلوچ کو حق ہے کہ وہ سوال کرے کہ یہ کون سی معصومیت ہے جو بندوق کی حفاظت میں کام کرتی ہے؟
بلوچ نوجوان اب جان چکا ہے کہ جمہوریت صرف تب تک خوبصورت لگتی ہے جب تک اس کے خدوخال بلوچستان میں خون سے نہیں ڈھلتے۔ ہم نے وہ عدلیہ دیکھی ہے جو مسخ شدہ لاش پر “ناکافی ثبوت” کا فیصلہ دیتی ہے۔
یہی وہ لمحہ ہے جہاں بلوچ دانش کی طنز، تمسخر نہیں، بلکہ عقلی مزاحمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم ہنستے ہیں، تاکہ رو نہ پڑیں اور جو ہنسی سے بھی خوفزدہ ہو جائے، سمجھ لیجیے وہ ہتھیار سے پہلے ہی ہار چکا ہے۔
جب ریاست اپنے الفاظ میں جبر، اپنے عدالتی فیصلوں میں قتل، اور اپنے ترقیاتی منصوبوں میں نسل کشی چھپاتی ہے، تو مزاحمت محض نعرہ نہیں رہتی، وہ لغت کی بازیافت بن جاتی ہے۔ بلوچ مزاحمت اب صرف بندوق کا ردعمل نہیں، یہ ایک ایسی فکری تحریک ہے جس نے ریاست کے بنائے ہوئے ہر “سچ” کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہے جب فوکو کا وہ تصور کہ “طاقت صرف جسم پر عمل نہیں کرتی بلکہ “سچ” پر اختیار رکھتی ہے۔” پوری شدت سے سامنے آتا ہے۔ پنجابی ریاست نے بلوچ پر فقط ٹینک نہیں چلائے، اس نے بیانیے، نصاب، میڈیا، حتیٰ کہ رشتہ داری کے مفہوم تک کو ریڈ زون میں داخل کر دیا۔ لیکن بلوچ نے نہ صرف جبر کو پہچانا، بلکہ اُس “سچ” کو بھی رد کر دیا جو ریاست نے گھڑا تھا۔
اب بلوچ نوجوان جب سوال کرتا ہے کہ “یہ ملک ہے یا فوجی کمپنی؟”، تو دراصل وہ ونٹگنسٹائن کے اس سوال کو بلوچ پہاڑوں میں دہرا رہا ہوتا ہے کہ “زبان وہ خول ہے، جس میں حقیقت بند کی جاتی ہے۔” اور ہم نے اس خول کو توڑا ہے۔
ماہ رنگ بلوچ، سمی دین بلوچ، بیبو بلوچ ، گل زادی اور درجنوں خواتین انقلابیوں کی گرفتاری اس نظام کی اس بوکھلاہٹ کا اظہار ہے جس میں مرد کے بعد عورت نے بھی غلامی سے انکار کر دیا ہے۔ ان گرفتاریوں میں محض قانون کی بےرحمی نہیں، بلکہ نوآبادیاتی خوف کی جھلک ہے۔ وہ خوف کہ اب بیانیہ ریاست کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، خوف کہ اب عورت صرف عزت نہیں، اِنتقام کا شعور بھی ہے؛ خوف کہ اب ہر چیخ، ایک فکری مقدمہ ہے، اور ہر گرفتاری، بیانیہ شکست کی علامت ہے۔
یہ وہ مقام ہے جہاں بلوچ کی اجتماعی مزاحمتی دانش کی ہر تحریر و تقریر ایک بندوق جیسی ہوتی ہے۔ وہ گولی نہیں مارتی، مگر نشانہ لیتی ہے۔ اور یہ نشانہ ریاستی بیانیے کے بیچوں بیچ لگتا ہے، جہاں وہ خود کو مہذب، جمہوری، اور ترقی یافتہ سمجھتی ہے۔
ہم جان چکے ہیں کہ یہ ترقی “بموں” کے ساتھ آتی ہے، یہ جمہوریت “مسخ شدہ لاش” کے اوپر بیلٹ پیپر رکھتی ہے، اور یہ مہذب ریاست “جیل میں بیٹھی لڑکی” کو دہشتگرد کہتی ہے۔ لیکن بلوچ لغت اب تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں دہشتگرد وہ ہے جو شناخت چھینے، یہاں ترقی وہ ہے جو جبر کی مخالفت میں قدم اٹھائے، اور یہاں حب الوطنی وہ ہے جو نوآبادیاتی ریاست کو مسترد کرے۔
یہ بلوچ کا اجتماعی اعلان ہے کہ ہم اس کالونیل ریاست کی کسی لغت کو قبول نہیں کرتے، ہم اس بیانیے کے تمام دروازے بند کرتے ہیں جہاں غلامی کو وفاداری بنا کر پیش کیا جائے اور ہم ان سچائیوں کو مانتے ہیں جو ہمارے شہیدوں کے لہو سے لکھے گئے ہیں، نہ کہ ان سچائیوں کو جو کسی نیوز چینل کے اسکرپٹ میں ریاستی مفاد کے تابع لکھی گئی ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ مزاحمت کے بعد جو لغت بچتی ہے وہی حقیقی لغت ہوتی ہے۔ اور وہ لغت، بلوچ نے اپنے خون سے لکھنا شروع کر دیا ہے۔
یہ جنگ اب محض بلوچ سرزمین کی آزادی کی جنگ نہیں رہی، یہ شعور کے اقتدار کی جنگ ہے۔ اور جس دن قومیں لغت پر اپنی ملکیت کا اعلان کرتی ہیں، وہ دن صرف ایک سیاسی عمل نہیں، ایک فکری انقلاب ہوتا ہے۔ بلوچ قوم نے یہی کر دکھایا ہے۔ اُس نے ریاست کے بنائے ہوئے ہر استعارے، ہر دعوے، ہر مقدس جھوٹ کو مسترد کرکے، اپنے دکھ، اپنے سوال، اور اپنے انکار سے ایک نئی لغت تخلیق کی ہے، ایسی لغت جس میں “خاموش عورت” ایک تنظیم ساز ہے، “ناراض نوجوان” ایک فکری مؤرخ، اور “دہشتگرد پہاڑ” ایک مظلوم یادگار ہے۔ یہ مزاحمت محض بندوق سے نکلنے والے بارود کی نہیں یہ وہ فکری دھماکہ ہے جو زبان کی جڑوں میں لگایا گیا ہے۔
جب پنجابی ریاست “قومی دھارا” کی بات کرتی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں، کیا اُس دھارے میں اُن لوگوں کے لیے بھی جگہ ہے جن کے بیٹوں کی لاشیں آدھی رات کو دروازے پر پھینکی جاتی ہیں؟ جب وہ “ترقی” کا پرچار کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں، کیا وہی ترقی جو قبرستان کے راستے سے آتی ہے؟ اور جب وہ “قانون” کی بات کرتی ہے، تو ہم فقط ہنس دیتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قانون صرف اُسی کے لیے ہوتا ہے جو طاقت کو قانون مانے۔
یہ وہ فیصلہ ہے جو بندوق کے زور پر نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ وہ انکار ہے جو جیل کی سلاخوں سے، عدالت کے فیصلوں سے، میڈیا کے بیانیے سے یا اقوام متحدہ کے خاموش کاغذوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ اب ہم نہ صرف زندہ ہیں، بلکہ لغت لکھنے کے عمل میں شریک ہیں۔
ہم اپنے قاتل کو “مزدور” نہیں کہتے، ہم اپنی قید عورت کو “قربانی کی علامت” نہیں بلکہ ہم اُسے سیاسی استعارہ کہتے ہیں، ہم ریاست کو “ماں” نہیں مانتے، ہم اُسے قابض نوآبادیاتی انتظامیہ کہتے ہیں، ہم آزادی کو کوئی خواب نہیں مانتے، ہم اُسے واجب الادا حقیقت کہتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ غلامی صرف گولی سے نہیں ختم ہوتی، غلامی اُس وقت مرتی ہے جب محکوم اپنی لغت خود بنا لے۔ اور اب چونکہ ہم اپنی بے انتہا قربانیوں سے لغت کے مالک ہوچکے ہیں، لہٰذا جنگ اب صرف آزادی کی نہیں، بلکہ لغت کی حاکمیت کی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں۔
دی بلوچستان پوسٹ: اس تحریر میں پیش کیئے گئے خیالات اور آراء لکھاری کے ذاتی ہیں، ضروری نہیں ان سے دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک متفق ہے یا یہ خیالات ادارے کے پالیسیوں کا اظہار ہیں۔